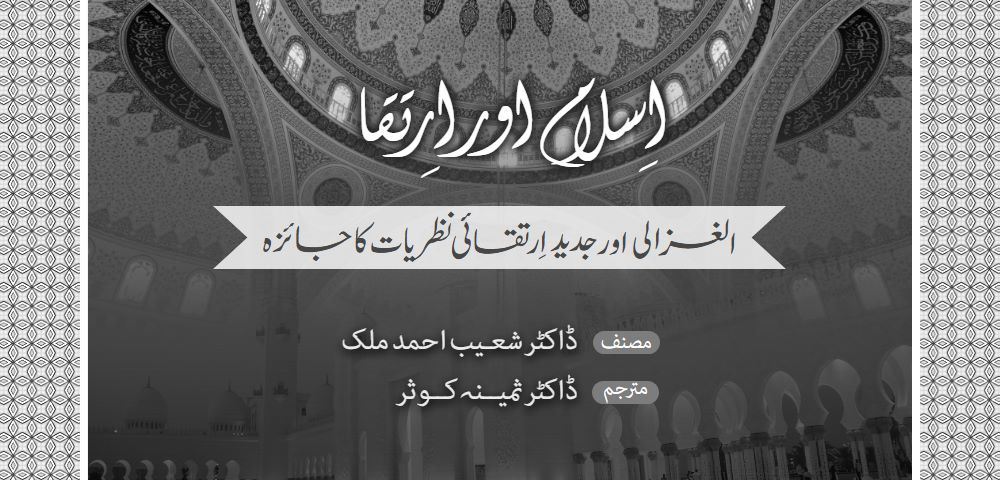اختصاصِ آدم
(Adamic Exceptionalism)
داؤد سلیمان جلاجل (David Solomon Jalajel) وہ واحد مفکر ہیں جنہوں نے اختصاصِ آدم (Adamic exceptionalism) کی اصطلاح پر مبنی موقف پیش کیا ہے۔ ان کی یہ تجویز نہایت باریک بینی کے ساتھ وضاحت کی متقاضی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، مالک (2018؛ 2019) اور گیسوم (2011b؛ 2016) کا خیال تھا کہ جلاجل کو تخلیق پسند (creationist) مکتبِ فکر میں شامل کیا جانا چاہیے، مگر جلاجل کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت اسلام اور نظریہ ارتقا کے مابین تطابق پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ تاہم، مالک (2020) نے بعد میں جلاجل کی تجویز سے متعلق اپنی سابقہ رائے واپس لے لی۔ جلاجل واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اہلِ سنت کے کلامی مکاتبِ فکر، یعنی اشعریت، ماتریدیت اور اثریت کے منہجی اصولوں سے ماخوذ کر رہے ہیں (جلاجل 2009، ص 3–8)۔ اگر انہی مکاتبِ فکر کو بحث کا زاویہ نظر بنایا جائے تو جلاجل کے مطابق ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جو ارتقا کی اس قدر سخت اور بظاہر غیر ضروری تردید کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمؑ کے معاملے میں کیا کہا جائے؟
جلاجل کے مطابق اہلِ سنت کے تاویلی اصول جو وہ زیرِ بحث لاتے ہیں، اس بات کی کوئی گنجائش فراہم نہیں کرتے کہ آدمؑ کو والدین کے ساتھ تصور کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، آدمؑ ایک معجزانہ تخلیق ہیں اور ان کی پیدائش والدین کے بغیر ہوئی ہے۔ یہ موقف اہلِ سنت کے ہاں غیر متنازع ہے، کیونکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ معجزات ممکن ہیں اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر آدمؑ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو اسے ارتقا کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کیا جائے؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں جلاجل اپنی اصل علمی جدت یعنی توقف کو بروئے کار لاتے ہیں۔
لفظ توقف کے معنی ہیں ’’فیصلہ یا عقیدہ معطل رکھنا‘‘۔ مثال کے طور پر، جب کسی شخص کے سامنے کوئی ایسا سوال آئے جس کے متعدد ممکنہ جوابات ہوں اور وہ یقینی علم نہ ہونے کے باعث کسی ایک کا انتخاب نہ کرے، تو یہ عمل توقف کہلاتا ہے۔ اسلامی متون کے تناظر میں توقف کے دو بنیادی استعمالات ہیں:
(1) فقہ اور علمِ حدیث میں،
(2) عقائد اور کلام میں۔
فقہ اور حدیث کے تنقیدی مباحث میں توقف کا مطلب ہے کسی مسئلے پر فیصلہ نہ دینا جب تک متعارض دلائل میں ترجیح نہ مل جائے۔ یہ عارضی حالت ہے، یعنی فیصلہ موخر رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی قوی دلیل یا نیا محقق اسے حل کر سکے (فرحات 2019، ص 177)۔
مثلاً، اگر دو احادیث ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہوں اور محدث فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکے کہ کس کو ترجیح دی جائے، تو وہ توقف اختیار کرتا ہے۔ تاہم، ممکن ہے بعد میں کوئی دوسرا عالم اس تضاد کو رفع کر دے۔ اس کے برعکس، کلامی توقف ایک مستقل اور واجب علمی رویہ ہے ، یعنی کسی ایسے معاملے کو ’’نامعلوم‘‘ قرار دینا جس پر وحی خاموش ہے (غامدی 2016، ص 32)۔ مثال کے طور پر، ڈائنو سارز (dinosaurs) کا معاملہ لے لیجیے۔ قرآن و سنت میں ان کے وجود یا عدمِ وجود پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا شریعت کی رو سے کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ ’’اسلام ڈائنو سارز کو رد کرتا ہے‘‘ یا ’’ان پر ایمان لانا واجب ہے‘‘ دونوں غلط اور گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرنا ہے جو اللہ نے خود نہیں کہی۔
یہ اصول واضح کرتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں وحی خاموش ہو، تو اس کی بابت اثبات یا نفی دونوں حرام ہیں۔ یعنی ڈائنو سارز پر ایمان لانا بھی شرعاً لازم نہیں اور انکار بھی لازم نہیں۔ ایسے معاملات میں تمام ممکنہ آرا برابر طور پر درست اور قابلِ قبول ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت سے متعارض نہیں۔ اسی اصولی تصورِ توقف کو جلاجل اپنی بنیادی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ وحی آدمؑ کے سوا دیگر انواعِ انسانی کی تخلیق کی تفصیلات پر خاموش ہے، اس لیے مسلمان کے لیے ارتقا کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا دونوں موقف دینی طور پر ممکن اور قابلِ قبول ہیں۔ یوں جلاجل کے نزدیک اسلام اور نظریہ ارتقا کے مابین کوئی حقیقی تصادم نہیں رہتا، اور یہی ان کے تصورِ اختصاصِ آدم کی علمی بنیاد ہے۔
کلامی توقف کو تفویضِ معنی سے بھی الگ سمجھنا چاہیے۔ تفویضِ معنی اُس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی نص کا ظاہری مفہوم کسی وجہ سے محلِ اشکال ہو اور اسے قابلِ قبول مفہوم تک پہنچانے کے لیے دوبارہ تعبیر یا تاویل کی ضرورت پیش آئے۔ ایسی صورت میں مفسر دو راستے اختیار کر سکتا ہے: یا تو وہ ایک معقول اور غیر متعارض تاویل تجویز کرے جو اشکال کو دور کر دے، یا پھر وہ نص کے ظاہری معنی کو رد کرتے ہوئے، اس کے حقیقی معنی کو اللہ کے سپرد کر دے اور ایمان رکھے کہ جو مفہوم اللہ نے مراد لیا، وہی درست ہے۔ یہ طرزِ عمل اُن متشابہ یا پیچیدہ نصوص کی تعبیر کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جن کا ظاہری مفہوم کسی عقلی یا ایمانی اشکال کا باعث بن سکتا ہو۔ اس کے برعکس، توقفِ کلامی (جسے یہاں اختصاراً توقف کہا گیا ہے) کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے معاملے میں بالکل بھی رائے قائم نہ کی جائے جس پر نصوصِ شرعیہ مکمل طور پر خاموش ہوں۔ یعنی یہاں توقف تاویل یا تفویض کا متبادل نہیں بلکہ ایک لاعلمی پر مبنی ایمانی احتیاط ہے کہ جب وحی کسی امر کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، تو انسان بھی اس بارے میں کچھ نہ کہے۔ (اس تفریق کی مزید وضاحت آئندہ ابواب 9 اور 10 میں آئے گی۔)
ان بنیادی تصورات کی روشنی میں اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جلاجل اپنی علمی جدت کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان یہ مفروضہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدمؑ ہی پہلے انسان تھے، چنانچہ انسانی نسل کی ابتدا بھی ان ہی سے ہوئی۔ یہی تصور مالک کیلر (2011)، اور یاسر قاضی و نذیر خان (2018) جیسے مفکرین کے ہاں پایا جاتا ہے، جنہیں ہم پہلے زیرِ بحث لا چکے ہیں۔ یہ سب دراصل اختصاصِ آدم کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آدمؑ کی پیدائش معجزانہ تھی اور اسی لیے انسانوں کا ارتقائی ماخذ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
جلاجل (2018) اس روایت سے ہٹ کر ایک منفرد موقف پیش کرتے ہیں۔ وہ حضرت آدمؑ کی تخلیق اور انسانی نسل کی ابتدا کے مابین لازم تعلق کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق، جب آدمؑ آسمان سے زمین پر اُتارے گئے (جیسا کہ اکثر علما کا موقف ہے)، تو قرآن نے نہ یہ کہا کہ زمین پر اُس وقت انسان موجود نہیں تھے، اور نہ ہی یہ کہا کہ موجود تھے۔ یعنی قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ لہٰذا اگر نصوص میں کوئی صریح بیان نہیں، تو اس موضوع پر توقفِ کلامی لازم ہے، یعنی دونوں امکانات یکساں طور پر ممکن ہیں۔ یہ بھی کہ آدمؑ کے نزول سے قبل زمین پر انسان موجود تھے، اور یہ بھی کہ نہیں تھے۔ چونکہ وحی اس بارے میں خاموش ہے، اس لیے دونوں امکانات شرعاً درست اور قابلِ قبول ہیں۔
اگر اس استدلال کو مانا جائے، تو ایک قابلِ تصور مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمؑ زمین پر اُترے اور وہاں پہلے سے ارتقائی عمل سے پیدا ہونے والے انسان موجود تھے۔ آدمؑ کی نسل نے ان انسانوں سے اختلاط کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس پر بھی توقف واجب ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی تصریح نہیں۔ پہلی صورت میں یہ ممکن ہے کہ بعد کی تمام نسلِ انسانی بیک وقت دو نسبتوں کی حامل ہو۔ یعنی ایک نسبت آدمؑ سے (بطور معجزانہ تخلیق)، اور دوسری نسبت مشترکہ حیاتیاتی ارتقا سے، جو تمام جانداروں کو ایک ارتقائی زنجیر میں جوڑتا ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ آدمؑ کا معجزہ وحی کی بنیاد پر یقینی ہے لیکن قرآن اس امکان کی نفی نہیں کرتا کہ آدمؑ کے نزول کے وقت زمین پر ارتقائی عمل سے پیدا شدہ انسان موجود رہے ہوں۔ لہٰذا جلاجل کے موقف کو تخلیقیت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ غیرِ انسانی ارتقا کے قائل ہیں۔ اسی طرح اسے "انسانی استثنائیت" (human exceptionalism) بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ اس امکان کو مانتے ہیں کہ آج کے تمام انسانوں کی ایک حیاتیاتی نسبت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو آدمؑ سے پہلے تک جاتی ہو۔
تاہم، اسے "کلی ارتقا پسندی" (no exceptions camp) بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آدمؑ کی تخلیق ایک معجزانہ استثنا ہے۔ اسی لیے جلالجل کے موقف کو اختصاصِ آدم کہنا زیادہ درست اور جامع ہے۔ یعنی ایسا نظریہ جو آدمؑ کی معجزانہ تخلیق کو تسلیم کرتے ہوئے ارتقا کے دیگر پہلوؤں سے ہم آہنگی کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ جلاجل کے نزدیک حضرت آدمؑ سائنسی تحقیق کا نہیں بلکہ ایمان کا موضوع ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک معجزانہ وجود ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ماقبل تاریخ کی ایک ایسی منفرد شخصیت ہیں جن کا ذکر صرف وحی کے ذریعے ہوا ہے۔ لہٰذا ان کے وجود کو سائنسی ذرائع سے ثابت نہیں کیا جا سکتا،اور نہ ہی ان کی معجزانہ تخلیق کو ارتقائی نظریے کے سائنسی دعووں پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ آدمؑ کی تخلیق ایک ایماناً مسلم معجزہ ہے، مگر اس کا انسانی ارتقا سے سائنسی طور پر کوئی تصادم نہیں، کیونکہ ان کے اولین ذریت کے نکاح یا ارتقائی ملاپ کے بارے میں وحی خاموش ہے، اور اسی وجہ سے یہاں توقف اختیار کرنا لازم ہے۔ چنانچہ جلاجل کے مطابق مسلمان انسان کے ارتقائی نظریے کو اس کے سائنسی شواہد کی بنیاد پر قبول یا رد کر سکتے ہیں، لیکن اسے آدمؑ کی داستان سے جوڑنا نہ ضروری ہے، نہ واجب۔
اس مکتبِ فکر کے حامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارتقائی عمل سے کسی کو استثنا حاصل نہیں۔ ان کے نزدیک غیرِ انسان، انسان اور کم از کم اُن لوگوں کے لیے جو حضرت آدمؑ کے تاریخی وجود کے قائل ہیں، آدمؑ بھی مشترک نسب (common ancestry) کا حصہ ہیں۔ یوں یہ گروہ سائنسی نظریات کو بنیادی طور پر درست تسلیم کرتا ہے، جو تخلیقیت پسند مکتب کے برعکس موقف ہے۔البتہ انہیں یہ چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ باب سوم میں بیان کردہ قرآنی تخلیقی بیانیے کے ساتھ اپنے اس نظریے کو ہم آہنگ کس طرح کیا جائے۔
کچھ مفکرین اس چیلنج کا جواب استعاراتی یا تمثیلی قرات (metaphorical interpretation) کے ذریعے دیتے ہیں۔ اردن کی حیاتیاتی ماہر اور محقق رنا دَجّانی اس طرزِ فکر کی نمایاں نمائندہ ہیں۔ وہ اپنی بات دو بنیادی اصولوں پر قائم کرتی ہیں:
(الف) قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کے اصولوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔
ان کے الفاظ میں:
قرآن سائنسی نظریات کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے نہیں اترا بلکہ یہ اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ لہٰذا ہر سائنسی دریافت کے لیے ہم قرآن میں ثبوت تلاش کرنے کے پابند نہیں۔(Dajani 2016, 146)
(ب) انسان کی تفسیری صلاحیت محدود ہے۔ چونکہ تفسیر ایک انسانی عمل ہے اور انسان زمان و مکان کے دائرے میں مقید ہے، اس لیے وہ ہمیشہ خطا کا امکان رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ علم میں اضافہ نئی بصیرتیں پیدا کرتا ہے، لہٰذا تفسیر میں جمود نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اجتہاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث نقل کرتی ہیں:
"جب قاضی فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، پھر درست ثابت ہو تو اسے دو اجر ملیں گے، اور اگر اجتہاد میں غلطی کرے تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔"(Bukhārī 7352)
ان اصولوں سے دجانی یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ قرآن میں بیان کردہ آدمؑ کا قصہ اور دیگر کہانیاں لفظی طور پر نہیں لی جانی چاہییں۔ یہ محض تمثیلیں ہیں جن کے ذریعے اخلاقی اور فکری اسباق دیے گئے ہیں۔ انسانی ارتقا ایک تدریجی عمل تھا جو مختلف انسانی گروہوں میں وقوع پذیر ہوا، جو سابقہ نسلوں سے ارتقا کے ذریعے وجود میں آئے۔(Dajani 2016, 146)
اپنے نظریے کے حق میں وہ دو مزید لسانی نکات پیش کرتی ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اگر درست طور پر سمجھے جائیں تو ارتقا اور اسلام کے درمیان موجود بظاہر تنازع ختم ہو جاتا ہے۔
(1) لفظ "خَلَقَ" (خلق)
دجانی کے مطابق "خلق" کا مطلب ہمیشہ "فوری تخلیق" نہیں ہوتا، بلکہ اسے "تدریجی ارتقا" کے مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق
"لفظ ‘خلق’ لازماً دفعی تخلیق کے لیے نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تخلیق ایک طویل زمانی مدت میں انجام پائی ہو۔ مسلمانوں کو یہ ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ سورج اور ستاروں کو بننے میں اربوں سال لگے، مگر جب جانداروں خاص طور پر انسان کے ارتقائی عمل کی بات آتی ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ وقت ایک جہت ہے اور اللہ تمام جہات سے بلند ہے، اس لیے وہ وقت کے تابع نہیں۔ لہٰذا کسی شے کی تخلیق میں طویل عرصہ لگنا اللہ کے اختیار کے خلاف نہیں۔ (دجانی 2016، ص 145–146) ان کے مطابق لفظ "خلق" کا مفہوم وسیع ہے، جو فوری تخلیق اور ارتقائی عمل دونوں کو محیط کر سکتا ہے۔
(2) لفظ "أَحْسَن" (اَحسن)
وہ دو قرآنی آیات کی مثال دیتی ہیں: جس نے ہر چیز کو جو اُس نے پیدا کی، اَحسن بنایا: اُس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی۔ (السجدہ 32:7)
بیشک ہم نے انسان کو اَحسنِ تقویم میں پیدا کیا۔ (التین 95:4)
دجانی کے نزدیک یہاں "اَحسن" کا مطلب سب سے زیادہ مناسب ہے، نہ کہ"سب سے اعلیٰ"۔ وہ لکھتی ہیں:
اللہ نے تمام مخلوقات کو ان کے ماحول کے لیے سب سے زیادہ مناسب حالت میں پیدا کیا۔ انسان بھی مٹی سے بنا، جو تمام مخلوقات کی اصل ہے۔ اَحسنِ تقویم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، بلکہ یہ کہ وہ اپنے ماحول کے لیے بہترین موزونیت رکھتا ہے۔ یہ دراصل ارتقائی موافقت (evolutionary adaptation) کی قرآنی تائید ہے۔(Dajani 2012, 349)
اسی طرزِ فکر کے ایک اور حامی مشہور پاکستانی شاعر اور فلسفی علامہ محمد اقبال ہیں۔ وہ دیگر تہذیبوں کی مثالوں سے رہنمائی لیتے ہیں اور قرآن مجید میں مذکور واقعہ آدم کو ایک تاریخی یا لفظی واقعہ سمجھنے کے بجائے علامتی اور استعاراتی معنی میں تعبیر کرتے ہیں (اقبال 2012، ص 65)۔
اقبال لکھتے ہیں:
لیکن ہمارے مسئلے کی بہتر تفہیم کی کنجی اُس روایت میں پوشیدہ ہے جسے سقوطِ انسان (Fall of Man) کہا جاتا ہے۔ اس روایت میں قرآنِ مجید نے اگرچہ قدیم علامات کے بعض اجزا کو برقرار رکھا ہے، مگر اس میں بنیادی تبدیلی کر کے اس کو بالکل نیا معنوی رخ عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ کہ وہ بعض روایات و اساطیر کو جزوی یا کلی طور پر نئے فکری معانی سے ہمکنار کرتا ہے تاکہ انہیں زمانے کی ترقی یافتہ روح کے مطابق ڈھال سکے ، یہ نہایت اہم نکتہ ہے جسے عموماً مسلم اور غیر مسلم دونوں محققینِ اسلام نے نظر انداز کیا ہے۔ درحقیقت، قرآن کا مقصد ان روایات کو بیان کرنا تاریخی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ انہیں اخلاقی یا فلسفیانہ معنویت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ہر زمانے کے انسان کے لیے آفاقی پیغام بن جائیں۔(Iqbal 2012, 65)
وہ مزید لکھتے ہیں:
قرآن جب انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو وہاں بشر یا انسان کے الفاظ استعمال کرتا ہے، نہ کہ 'آدم'۔'آدم' قرآن میں دراصل انسان کی خلافتِ ارضی کی علامت ہے، نہ کہ کسی ایک تاریخی فرد کا نام۔(Iqbal 2012, 66)
کچھ مفکرین صرف استعاراتی تعبیر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اُنہیں قرآن میں ارتقائی مفاہیم کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کی بعض آیات میں انسان اور حیات کی تدریجی تخلیق کے ایسے اشارات موجود ہیں جنہیں نظریۂ ارتقا کے ساتھ ہم آہنگ طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔
الجزائری ماہرِ فلکیات نضال قسوم (Nidhal Guessoum) اس طرزِ فکر کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ وہ اسلام اور نظریۂ ارتقا کے درمیان تطبیق کے لیے تین بنیادی تفسیری اصول پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ابنِ رشد کے "عدمِ تعارض" (no possible conflict) کے اصول کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ وحی اور حقیقت کے درمیان کسی بھی قسم کا تصادم ممکن نہیں۔ یعنی اگر کوئی سائنسی حقیقت ثابت ہو جائے، تو اس کی تردید دین کی نفی نہیں بلکہ فہمِ دین میں خامی کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرے اصول میں وہ حرفی (Literal) سوچ سے گریز پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق تخلیق پر ظاہری یا حرفی انداز میں یقین رکھنے والی ذہنیت ہی اصل رکاوٹ ہے، جو ہر بات کو صرف لفظی مفہوم میں محدود کر دیتی ہے اور قرآن کو نئی علمی تاویلات سے روک دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:
آج مسلمانوں کے لیے ارتقا کا سب سے بڑا مسئلہ آدمؑ کی ذات ہے۔ بہت سے علما یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آدمؑ سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ارتقا کو یکسر ردّ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک حرفی ذہنیت کا نتیجہ ہے جو تخلیق کو ایک سادہ تاریخی واقعہ سمجھتی ہے۔(Guessoum 2010, 828)
تیسرے اصول میں وہ مختلف قراتوں کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ نضال قسوم کے نزدیک قرآن کی ایک سے زیادہ علمی و فکری تعبیرات ممکن ہیں، بشرطیکہ وہ عقلی اور سائنسی بنیادوں پر استوار ہوں۔
ان کے الفاظ میں:
میں انتہاپسندانہ فکری رویّوں کے خلاف ہوں۔ میں ہمیشہ قرآن کی متعدد اور تہہ دار تعبیرات کی حمایت کرتا ہوں تاکہ انسان مختلف علمی ذرائع، بشمول سائنس، سے مدد لے کر متن کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔(Guessoum 2011a, 64)
نضال قسوم کے مطابق بعض احادیث مثلاً آدمؑ کے ساٹھ ہاتھ قد والی روایت سائنسی حقائق سے بظاہر متصادم دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کی تمثیلی تعبیر ممکن ہے۔ جہاں روایت اور علم میں تضاد محسوس ہو، وہ یہی طرزِ عمل وہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کا ظاہری مفہوم سائنس سے متصادم لگے،
تو اس کی تاویل علامتی طور پر کرنی چاہیے۔ بشرطیکہ روایت صحیح ہو۔ کیونکہ یہ وہی طریقہ ہے جو مسلمانوں نے ہمیشہ نص و عقل کے ظاہری تعارض میں اختیار کیا ہے۔ (Guessoum 2010, 829) اسی طرح وہ قرآن میں بشر اور انسان کے الفاظ کے درمیان ایک ارتقائی درجہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو انہوں نے محمد شحرور سے اخذ کی ہے۔ شحرور کے مطابق: "بشر‘ ارتقا کے اس مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے جب انسان حیاتیاتی اعتبار سے موجود تو تھا مگر ذہنی و روحانی بیداری سے محروم تھا، اور 'انسان' اُس مرحلے کو ظاہر کرتا ہے جب اللہ نے اُس میں اپنی روح پھونکی اور وہ شعور و ادراک کا حامل بنا۔" (Guessoum 2011a, 313–314)
یوں شحرور اور قسوم کے نزدیک قرآن میں بشر اور انسان کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے، اور یہی فرق ارتقا کے حق میں ممکنہ ہم آہنگ قرات مہیا کرتا ہے۔
ان تمام مفکرین دجانی، اقبال اورقسوم کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قرآن کو جامد یا محض لفظی انداز میں نہیں بلکہ عصرِ حاضر کی علمی و فکری بصیرتوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن کا مقصد تخلیق کے سائنسی مراحل بیان کرنا نہیں، بلکہ انسانی وجود کے اخلاقی، فکری اور روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کو نظریہ ارتقا سے متصادم سمجھنا دراصل نصوص کے محدود فہم کا نتیجہ ہے، نہ کہ مذہب اور سائنس کے درمیان کسی حقیقی تضاد کی علامت۔
پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد بھی بشرو انسان کی قرآنی تفریق کو قبول کرتے ہیں (Arien 2019)۔ ان کے نزدیک انسان دراصل روحِ غیر مادی (immaterial soul) اور جسمِ انسانی (physical body) کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس تصور کو قرآنِ مجید کے الفاظ"بشر" اور"انسان" کے عین مطابق قرار دیتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق، "بشر" کا اطلاق حیاتیاتی اعتبار سے کسی بھی نوع (species) پر ہو سکتا ہے جو جنسِ "ہومو (Homo) " سے تعلق رکھتی ہو جس میں ہومو سیپیئنز (Homo sapiens) یعنی موجودہ انسان بھی شامل ہیں۔ جبکہ"انسان" اس بشر پر بولا جاتا ہے جس میں روح پھونک دی گئی ہو، یعنی جو حیوانی وجود سے ماورائی شعور کی سطح پر پہنچ گیا ہو۔ اس مفہوم کی تائید میں وہ درج ذیل آیات پیش کرتے ہیں:
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ (القرآن 38:71)
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں خشک بجتی ہوئی مٹی، جو سیاہ گارے سے بنی ہے، سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ (القرآن 15:28)
ڈاکٹر اسرار احمد ان آیات کی تفسیر میں یوں تبصرہ کرتے ہیں:
ان آیات میں آنے والا لفظ "بشر" عام طور پر انسانی نوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے"ہومو (Homo)" نسل کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی جانداروں کا وہ حیاتیاتی خاندان جس سے آج کا انسان، ہومو سیپیئنز (Homo sapiens)، تعلق رکھتا ہے۔ ماہرینِ حیاتیات کے مطابق ہومو نسل کم از کم بیس لاکھ سال سے زمین پر موجود ہے، جبکہ جدید انسان (modern humans) سب سے پہلے بالائی عہدِ حجری (Upper Palaeolithic) دور میں ظاہر ہوئے۔ اسی بنیاد پر"بشر" کا لفظ ہومینِڈ (hominid) یا ہومینائیڈ (hominoid) مخلوق کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی ایسے جانداروں کے لیے جو حیاتیاتی طور پر انسانوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جن میں انسان (بطور جسمانی وجود، روحِ الٰہی کے نفخ سے پہلے) انسانوں کے فوسل شدہ آبا و اجداد، اور دیگر دو پاؤں پر چلنے والے جاندار (bipeds) شامل ہیں۔(Ahmad 2013, 46)
ڈاکٹر اسرار احمد اس مفہوم کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک "بشر" کو منتخب کیا گیا اور اسی میں روح پھونک کر اسے "آدم" بنایا گیا:
قرآن میں اس بات کا نہایت واضح اشارہ موجود ہے کہ آدمؑ دراصل ایک منتخب بشر تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اُن میں پھونک دی تو وہ آدم بن گئے۔ یہی وہ بنیادی اور ازلی حقیقت ہے جسے ملحد ارتقائی مفکرین دانستہ طور پر نظرانداز کر دیتے ہیں۔(Ahmad 2013, 46–47)
ڈاکٹر اسرار احمد اپنے موقف کو قرآن کی ان آیات سے تقویت دیتے ہیں جن میں "بشر" کی نوع میں سے بعض مخصوص افراد کے قدرتی انتخاب کا ذکر ہے، یعنی وہ افراد جنہیں نبوت کے لیے چنا گیا:
بے شک اللہ نے آدم، نوح، آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو تمام جہان والوں پر برگزیدہ کیا۔(القرآن 3:33)
ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ساخت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا،
سوائے ابلیس کے، جو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔(القرآن 7:11)
ڈاکٹر اسرار احمد اپنے موقف کو ان الفاظ پر سمیٹتے ہیں:
اللہ تعالیٰ کی جانب سے آدمؑ کا منتخب کیا جانا، اور اسی طرح انسانی نوع کے متعدد حیوانی جانداروں کی تخلیق کے بعد ایک مخصوص فرد کو 'آدم' کا لقب اور مقام عطا کیا جانا، نہایت معنی خیز اور بنیادی واقعہ ہے۔ یہ امتیاز دراصل روحِ الٰہی کے نفخ سے پیدا ہوا ۔ یعنی انسان کے حیوانی وجود میں ایک نیا اور بلند ترین مابعدالطبیعی عنصر شامل کیا گیا، جسے روحِ انسانی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ میں اپنی روح پھونکی اور یوں ان کے وجود میں روحانی عنصر سرایت کر گیا۔ اسی زاویے سے ہم اس قرآنی تعبیر کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اُس نے آدمؑ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ غالباً اس لطیف اشارے کی طرف اشارہ ہے کہ آدمؑ کا وجود دراصل دو مختلف حقیقتوں، ایک مادی جسمانی قالب اور دوسرا روحانی و معنوی حقیقت کا حسین امتزاج ہے۔(Ahmad 2013, 47)
بعض مفکرین نہ تو بشر اور انسان کی قرآنی تفریق کو مانتے ہیں اور نہ ہی تمثیلی یا استعاراتی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، وہ قرآنِ مجید کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ارتقائی فہم کی گنجائش نکل آئے۔
بھارتی نژاد امریکی ماہرِ اطفال ٹی۔ او۔ شناوس (T. O. Shanavas) اس سلسلے میں ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کے بارے میں روایتی تصور، یعنی اس بات کا کہ پوری انسانیت ایک ہی جوڑےآدم اور حوا سے پیدا ہوئی، جینیاتی اصولوں کے لحاظ سے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر انسانیت کا آغاز صرف ایک جوڑے سے ہوا ہوتا تو جینیاتی تنوع (genetic diversity) ممکن نہ رہتا، جس کے نتیجے میں نسلوں میں کمزوری اور بیماریوں کا پھیلاؤ یقینی تھا۔ اسی بنا پر وہ اس تصور کو مسترد کرتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا ایک ہی جوڑے سے ہوئی۔ شناوس کے نزدیک قرآن کا قصہ آدمؑ دراصل ایک ذہنی و روحانی حالت کی وضاحت کرتا ہے، نہ کہ ایک حیاتیاتی واقعہ کی۔ ان کے مطابق زمین پر انسان پہلے ہی موجود تھے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنی خاص عنایت سے منتخب کیا۔ یہی منتخب فرد آدمؑ کہلایا۔ اس مفہوم میں آدمؑ پہلے روحانی باپ (spiritual father) ہیں، نہ کہ حیاتیاتی اعتبار سے پہلے انسان (Shanavas 2010, 153160)۔ وہ اس مؤقف کی تائید اس بات سے بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں جنت کو ایک زمینی مقام کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ "آدم کے زمین سے اخراج" کے مادی مفہوم کے بجائے ایک شعوری تبدیلی کا استعارہ ہے۔ اسی طرح وہ آیت"اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں تدریجی مراحل سے گزارا (القرآن 71:14) کو ارتقائی تسلسل کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ شناوس کا نتیجہ کسی حد تک ڈاکٹر اسرار احمد کے نظریے سے مشابہ ہے۔ دونوں کے نزدیک انسان کی ابتدا ایک روحانی انتخاب کے ساتھ جڑی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمدبشر اور انسان میں واضح امتیاز قائم کرتے ہیں، جبکہ شناوس کے نزدیک یہ مرحلہ زیادہ علامتی اور نفسیاتی نوعیت رکھتا ہے۔
اسی موضوع پر ایک اور جدید مفکر، عراقی ماہرِ طبیعیات باسل الطائی (Basil Altaie)، بھی قرآن میں انسانی ارتقا کے اشارے تلاش کرتے ہیں۔ وہ تخلیقِ آدم کے قرآنی بیانیے کو لفظی طور پر لیتے ہیں لیکن اسے تین ارتقائی مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔
پہلا مرحلہ اس وقت کا ہے جب انسان کی تخلیق کے بنیادی اجزا یعنی مٹی، پانی اور دیگر عناصر زمین میں طویل عرصے سے موجود تھے۔ الطائی (2018، 131) کے مطابق قرآن میں مٹی اور گارے جیسے الفاظ کا ذکر اس حقیقت کی علامت ہے کہ انسان انہی قدرتی عناصر کے طویل کیمیائی و حیاتیاتی ارتقا سے وجود میں آیا۔ دوسرا مرحلہ انسان کی جسمانی ساخت کے ارتقا سے متعلق ہے، جس میں حیاتیاتی تشکیل اور مادی جسم کی تکمیل ہوئی (Altaie 2018, 132)۔ تیسرا اور آخری مرحلہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، جس کے نتیجے میں انسان کو شعور، ارادہ اور اخلاقی آگہی عطا ہوئی۔ الطائی کے نزدیک یہی لمحہ انسانی تہذیب کی ابتدا اور حیوانی وجود سے روحانی انسان بننے کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ وہ لکھتے ہیں:
انسان کی تخلیق کے تیسرے مرحلے میں جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو یہ ارتقائی عمل کا نقطہ انقلاب تھا۔ اس وقت انسان ایک غیر مہذب، غیر باشعور مخلوق سے ایک فہم رکھنے والی، سوچنے اور سمجھنے والی ہستی میں بدل گیا۔ یہ عقل اور شعور دراصل اللہ کے روحانی نفخ کا نتیجہ ہے۔ اسی سانس نے انسان کو محض ایک بلند درجہ حیوان سے ایک مکمل انسان میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو،جو دراصل قوانین فطرت کی علامت ہیں، انسان کے تابع کر دیا گیا تاکہ وہ دنیا کو سمجھے، دریافت کرے اور اسے اپنی بھلائی کے لیے مثبت طور پر استعمال کرے۔ (Altaie 2018, 134)
یوں شناوس اور الطائی دونوں اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ قرآنِ مجید میں انسان کے مادی اور روحانی دونوں ارتقا کے اشارے موجود ہیں۔ شناوس کے نزدیک آدمؑ ایک روحانی طور پر منتخب انسان ہیں، جبکہ الطائی کے نزدیک نفخِ روح وہ مرحلہ ہے جب انسان شعور و ارادہ کی سطح پر حیوانی ارتقا سے آگے بڑھ گیا۔ دونوں کے نزدیک اسلام اور نظریہ ارتقا میں کوئی حقیقی تضاد نہیں، بلکہ قرآن کا بیانیہ ارتقائی تسلسل اور روحانی انقلاب دونوں کو ایک وحدت کے طور پر پیش کرتا ہے ، یعنی انسان ایک حیوانی نوع سے ابھرتا ہے، مگر انسان بنتا ہے جب اس میں روحِ الٰہی پھونکی جاتی ہے۔ تاہم، باسل الطائی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آدمؑ کی تخلیق کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسے پہلو بھی موجود ہیں جو مخفی یا ماورائی (mystical / metaphysical) نوعیت رکھتے ہیں، اور جنہیں پوری طرح سمجھنا ممکن نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ قرآن میں آدمؑ کی تخلیق کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، ہم اسے پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔ اس کے برعکس، اس میں لازماً ایک نامعلوم اور مابعدالطبیعی (metaphysical) پہلو بھی شامل ہے، جو جنت میں آدمؑ کی تخلیق کے مرحلے سے متعلق ہے۔ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ آدمؑ کا جنت سے زمین پر اتارا جانا صرف ایک روحانی علامت تھا۔ دراصل قرآن کے ان غیر واضح اور پیچیدہ مقامات پر مزید غور و فکر اور علمی تحقیق کی ضرورت ہے، تاکہ ان میں پوشیدہ حکمتوں کو سمجھا جا سکے اور ان کے راز و اسرار کی عقدہ کشائی ہو سکے۔ (Altaie 2018, 135)
ملیشیا سے تعلق رکھنے والے ایک مفکر داؤد عبد الفتاح بیچلر (Daud Abdul-Fattah Batchelor) نے درجِ ذیل آیت کی ایک نہایت نئی اور بصیرت افروز تعبیر پیش کی ہے:
اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کو مت توڑو۔ بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ (القرآن، 4: 1)
بیچلر کے نزدیک اس آیت کا مفہوم محض آدم اور حوّا کی تخلیق تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی وحدت کے ایک گہرے روحانی اصول کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کے مطابق "نفس واحدۃ" کسی ایک مادی فرد کے بجائے انسانی نوع کی مشترکہ روحانی اصل کی علامت ہے۔ یعنی قرآن یہاں انسانیت کے مشترکہ ماخذ اور باہمی ربط کی طرف متوجہ کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی روحانی سرچشمے سے پیدا ہوئے ہیں، خواہ ان کی حیاتیاتی تخلیق مختلف زمانی مراحل سے گزری ہو۔
بیچلر (Batchelor 2017, 496–497) کے مطابق، سورۃ النساء کی آیت "نفس واحدۃ" میں مذکور "ایک جان" سے مراد کسی ایک شخص (یعنی آدمؑ) کے بجائے ایک ہی نطفے یا بارور شدہ بیضے (fertilised egg) سے پیدا ہونے والے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ ممکن ہے وہ ابتدائی زائیگوٹ (zygote) ایک نادر جینیاتی تبدیلی (rare genetic mutation) سے گزرا ہو، جس کے نتیجے میں ایک جڑواں لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے ، یعنی آدم اور حوّا۔ بیچلر کے نزدیک یہ تعبیر سائنسی طور پر ممکن ہے اور قرآن کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔ یوں وہ اس آیت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ آدم اور حوّا دراصل ایسے دو جڑواں بچے تھے جو پہلے سے موجود انسانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، نہ کہ بالکل مافوق الفطرت طور پر پیدا کیے گئے۔
یہ موقف بیچلر کو دوسرے جدید مسلم مفکرین سے ممتاز بناتا ہے، کیونکہ وہ پہلی بار قرآن میں آدم اور حوّا کے والدین کی موجودگی کی صریح تائید دیکھتے ہیں۔ جبکہ دیگر مفکرین، جو ارتقا کو اسلام کے ساتھ ہم آہنگ مانتے ہیں ،صرف اشارۃً (implicitly) یہ امکان تسلیم کرتے ہیں کہ آدم اور حوّا ایک ارتقائی سلسلے کے تسلسل سے آئے تھے اور ان کے حیاتیاتی والدین موجود تھے۔
ترک مفکر کانر تسلیمان (Caner Taslaman) ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جسے وہ "الٰہیاتی لاادریت" (theological agnosticism) کا نام دیتے ہیں۔ یہ تصور دراصل وہی ہے جسے پہلے ڈیوڈ سلیمان جلاجل نے توقف (tawaqquf) کے اصول کے طور پر پیش کیا تھا، البتہ تسلیمان اس تصور کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جلاجل کے نزدیک توقف صرف اُن انسانوں کے بارے میں ہے جو آدمؑ سے پہلے یا اُن کے ساتھ زمین پر موجود ہو سکتے تھے، یعنی وہ اس بات پر فیصلہ معطل رکھنے کا کہتے ہیں کہ آدمؑ سے پہلے انسانی نوع موجود تھی یا نہیں۔ جبکہ تسلیمان کے نزدیک توقف خود آدمؑ کی تخلیق پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، تسلیمان کا کہنا ہے کہ اسلامی وحی میں کوئی ایسی حتمی بات موجود نہیں جو ارتقا کو مکمل طور پر تسلیم یا رد کرتی ہو، بلکہ یہ اصول خود حضرت آدمؑ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اپنے مؤقف کے حق میں وہ تین نکات پیش کرتے ہیں۔
پہلا نکتہ احادیثِ ارتقا سے متعلق ہے۔ ان کے مطابق، وہ تمام روایات جن میں کائنات یا جانداروں کی تخلیق کے بارے میں ایسے بیانات ملتے ہیں
جو سائنسی یا ارتقائی مباحث سے متعلق ہیں، وہ تمام روایات موضوع (fabricated) ہیں۔ تسلیمان لکھتے ہیں:
احادیث کا وہ ذخیرہ جس میں نبی اکرم ﷺ کے اقوال و افعال جمع کیے گئے ہیں، اس میں کائنات اور جانداروں سے متعلق بعض ایسے اقوال بھی شامل ہو گئے ہیں جو دراصل من گھڑت ہیں اور انہیں غلط طور پر رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہ جھوٹی روایات زیادہ تر اس وقت اسلامی ذخیرے میں شامل ہوئیں جب مسلمانوں کا یہودی و عیسائی روایات (اسرائیلیات و مسیحیات) سے اختلاط ہوا اور ان کے بیانیے اسلامی لٹریچر میں شامل ہوگئے۔ (Taslaman 2020, 29–30)
تسلیمان احادیث کے حوالے سے ایک نہایت اہم فقہی و کلامی امتیاز بھی قائم کرتے ہیں، یعنی متواتر احادیث اور آحاد احادیث کے درمیان فرق۔
ان دونوں کی تفصیل باب 9 میں بیان ہوگی، لیکن یہاں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ متواتر حدیث مضبوط اور یقینی روایت کہلاتی ہے، جبکہ آحاد حدیث نسبتاً کم درجے کی اور ظنّی روایت ہوتی ہے۔ یہ فرق تسلیمان کے نزدیک اس لیے فیصلہ کن ہے کہ اس کے عقیدے پر براہِ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ان کے مطابق، ایمان اور عقائد کے بنیادی اصول صرف قوی (متواتر) احادیث پر قائم کیے جا سکتے ہیں، جبکہ کمزور یا آحاد روایات کو اس درجے کی حیثیت حاصل نہیں۔ چونکہ تخلیقِ کائنات، غیرِ انسانی حیات اور انسان کی ابتدا سے متعلق تمام تفصیلات زیادہ تر آحاد روایات پر مبنی ہیں، اس لیے تسلیمان کے نزدیک احادیث کا یہ ذخیرہ ارتقا کے مسئلے میں کوئی حتمی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:
ارتقا کے بارے میں اسلامی عقائد سے مطابقت یا عدمِ مطابقت کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کا متن ہی کافی ہے، کیونکہ اس باب میں احادیث اپنی کمزور سند اور غیر متواتر نوعیت کی وجہ سے اعتقادی بنیاد فراہم نہیں کر سکتیں۔ (Taslaman 2020, 30)
کانر تسلیمان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں تخلیقِ انسان اور ارتقا سے متعلق آیات صریح نہیں بلکہ قابلِ تاویل ہیں، یعنی ان کے معنی مختلف زاویوں سے سمجھے جا سکتے ہیں۔
مثلاً وہ آیت جس میں ارشاد ہے کہ "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان (نفس واحدۃ) سے پیدا کیا" (القرآن، 4: 1) اس آیت میں "نفس واحدۃ" کے بارے میں بیچلر نے کہا تھا کہ اس سے مراد ایک زائیگوٹ (zygote) یعنی بارور شدہ بیضہ ہے، لیکن تسلیمان (Taslaman 2020, 66) کے نزدیک یہاں مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک نوع یا جماعت (genus) ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ انسان کسی ایک فرد سے پیدا کیے گئے، بلکہ یہ کہ تمام انسان ایک ہی نسلی مآذ یا حیاتیاتی نوع سے پیدا ہوئے۔ یوں آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ "جس نے تمہیں ایک ہی نوع (ایک ہی مخلوقی صنف) سے پیدا کیا"۔ اس تعبیر کے مطابق، قرآن انسانیت کو کسی ایک فرد (یعنی آدمؑ) سے منسوب نہیں کرتا بلکہ ایک ہی حیاتیاتی نوع سے پیدا ہونے والی مخلوق کے طور پر بیان کرتا ہے۔ مزید برآں، تسلیمان (2020, 72–75) کے مطابق، قرآن میں آدمؑ کی جنت کوئی ماورائی جگہ نہیں بلکہ زمین پر ایک باغ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ زمین پر ہی پیش آیا، اور اس کا مقصد روحانی تربیت اور اخلاقی آزمائش کا بیان تھا، نہ کہ کسی آسمانی جنت سے نزول کا۔ اسی طرح وہ اس آیت کی بھی نئی تعبیر پیش کرتے ہیں، جس میں عیسیٰؑ اور آدمؑ کے درمیان تشبیہ دی گئی ہے: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی مانند ہے۔ (القرآن، 3: 59) عام طور پر مفسرین اس آیت سے آدمؑ کی معجزانہ تخلیق پر استدلال کرتے ہیں کہ جیسے عیسیٰؑ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ویسے ہی آدمؑ بغیر والدین کے پیدا ہوئے۔ لیکن تسلیمان اس تعبیر کو الٹ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن خود بیان کرتا ہے کہ: "عیسیٰؑ کی ماں تھیں اور وہ حمل اور ولادت کے عام انسانی عمل کے ذریعے پیدا ہوئے۔" (Taslaman 2020, 63) لہٰذا، اگر قرآن نے عیسیٰؑ اور آدمؑ کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی ہے ،تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمؑ کی پیدائش بھی فطری عمل کے ذریعے ہوئی ہو ، یعنی وہ بھی ایک ماں سے پیدا ہوئے ہوں اور حیاتیاتی اعتبار سے ارتقائی سلسلے کا حصہ ہوں۔
یوں تسلیمان عام قرآنی فہم کے برعکس یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ قرآن نہ تو آدمؑ کی معجزانہ تخلیق کا اثبات کرتا ہے، اور نہ ہی اسے قطعی طور پر رد کرتا ہے، بلکہ وحی اس معاملے میں خاموش ہے، اور یہی الٰہیاتی توقف (theological agnosticism) کا اصول ہے ،جو ان کے نزدیک اسلام اور نظریہ ارتقا میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔
تسلیمان کا تیسرا اور آخری استدلال معجزات کے بارے میں ایک لاادری (agnostic) مؤقف اختیار کرنے سے متعلق ہے۔ ان کے مطابق قرآنِ مجید معجزات کی نوعیت کے بارے میں خاموش ہے۔ یعنی یہ واضح نہیں کرتا کہ معجزات قدرت کے قوانین کو معطل کر کے پیش آتے ہیں یا انہی قوانین کے دائرے میں رونما ہوتے ہیں۔ تسلیمان کا کہنا ہے کہ چونکہ اللہ کی نیت یا طریقہ عمل ہمارے لیے براہِ راست معلوم نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کرتے وقت قدرتی قوانین کو منسوخ کیا یا نہیں کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں ماضی میں ماورائی یا غیر معمولی سمجھی جاتی تھیں، ممکن ہے وہ دراصل قدرتی قوانین کے تحت ممکن ہوں، بس اُس وقت انسان ان قوانین سے واقف نہیں تھا (Taslaman 2020, 92)۔
ان تمام نکات کو جمع کر کے تسلیمان (2020, 93) اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معجزات کے بارے میں ایک غیر یقینی مگر کھلا موقف اختیار کرنا ہی سب سے معقول ہے۔ وہ کہتے ہیں: اہلِ ایمان اس بات پر تو متفق ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی مداخلت یا تو قدرت کے قوانین کو معطل کر کے ہو سکتی ہے یا انہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے۔ دونوں امکانات درست اور قابلِ قبول ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ قدرت کے قوانین کو معطل کیے بغیر نئی انواع پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ان قوانین کو معطل کر کے نئی انواع پیدا نہیں کر سکتا۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں، اور چونکہ ہمیں اللہ کی نیت یا طریقہ تخلیق تک علم کی رسائی حاصل نہیں، اس لیے ہمیں کسی ایک امکان کو قطعی نہیں مان لینا چاہیے۔ قرآن کا متن ہمیں کسی ایک موقف کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اسی طرح معجزات کے معاملے میں بھی ہمیں الٰہیاتی لاادریت (theological agnosticism) کا رویہ اپنانا چاہیے۔
کمزور احادیث کے انکار، ارتقا سے متعلق قرآنی آیات کے تاویلی امکانات، اور معجزات کے بارے میں لاادری رویے، ان تینوں پہلوؤں کو یکجا کرتے ہوئے کانر تسلیمان اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دائرے میں نظریہ ارتقا کوئی عقیدہ شکن مسئلہ نہیں۔ ان کے نزدیک یہ تمام دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ارتقا کا نظریہ اسلامی وحی کے کسی بنیادی تصور سے متصادم نہیں، کیونکہ قرآن نے تخلیق کے تفصیلی طریقے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ یہی خاموشی اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمان کے لیے اس بارے میں کسی ایک موقف پر اصرار ضروری نہیں۔ تسلیمان اس موقف کو "الٰہیاتی لاادریت" (theological agnosticism) کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق، جب وحی کسی مسئلے پر قطعی حکم نہیں دیتی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ توقف اختیار کرے، نہ اسے ایمان کا جزو بنائے اور نہ انکار کا۔ اسی اصول کی روشنی میں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ارتقا کا نظریہ قرآن کے کسی بیانیے کو چیلنج نہیں کرتا، لہٰذا اس کی اسلام سے فکری ہم آہنگی ممکن ہے۔ یوں "No Exceptions Camp" یعنی وہ گروہ جو ارتقا کو کسی استثنا کے بغیر تسلیم کرتا ہے، اپنی فکری بنیاد مکمل کرتا ہے۔ یہ جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے تخلیق پسند مکتبِ فکر میں مختلف جہتوں سے دلائل موجود ہیں، ویسے ہی اس کی دوسری انتہا پر موجود مفکرین جو ارتقا کو مکمل طور پر قابلِ قبول سمجھتے ہیں ، بھی نہایت متنوع اور فکری طور پر پیچیدہ دلائل پیش کرتے ہیں۔
آئندہ باب میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان مختلف آرا میں سے کون سی آرا امام غزالی کے تفسیری و تاویلی منہج سے مطابقت رکھتی ہیں، اور وہ علمی و کلامی بنیادیں کیا ہیں جن کے تحت غزالی کا فہمِ قرآن جدید سائنسی مباحث سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔
References
1. Al-Jāḥiẓ. 1938a. Kitāb Al Ḥayawān. Volume 4. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī. Al-Jāḥiẓ.
2. 1938b. Kitāb Al Ḥayawān. Volume 1. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
3. Bayrakdar, Mehmet. 1983. “Al-Jāḥiẓ and the Rise of Biological Evolutionism.” Islam Quarterly, 21: 149–155.
4. Chittick, William C. 2013. “The Evolutionary Psychology of Jalal al-Dīn Rumī.” In Peter J. Chelkowski, ed. Crafting the Intangible: Persian Literature and Mysticism. University of Utah Press: Salt Lake City, 70–90.
5. Chittick, William C. 2017. “RUMĪ, JALĀL-AL-DĪN vii. Philosophy,” Encyclopædia Iranica. Accessed 5th February 2019. Available at: http://www.iranicaonline.org/ articles/rumi-philosophy.
6. Cook, Michael. 1999. “Ibn Qutayba and The Monkey.” Studia Islamica, 89: 43–74.
7. Dajani, Rana. 2016. “Evolution and Islam: Is There a Contradiction?” Paper Presented at Islam and Science: Muslim Responses to Science’s Big Questions, London and Islamabad.
8. de Boer, Tjitze J. 1903. The History of Philosophy in Islam. London: London Luzac. Draper, John William. 1875. History of the Conflict between Religion and Science. New York, NY: D. Appleton and Company.
9. Egerton, Frank N. 2002. “A History of the Ecological Sciences, Part 6: Arabic Language Science: Origins and Zoological Writings.” Bulletin of the Ecological Society of America, 83(2): 142–146.
10. Old texts, new masks 175 El-Bizri, Nader. 2014. The Ikhwan al-Safa and Their Rasail. Oxford: Oxford University Press.
11. Elshakry, Marwa. 2014. Reading Darwin in Arabic, 1860–1950. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
12. Fakhry, Majid. 2004. A History of Islamic Philosophy. New York, NY: Columbia University Press.
13. Futuyma, Douglas J., and Mark Kirkpatrick. 2017. Evolution. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
14. Ghafouri-Fard, Soudeh, and Seyed Mohammad Akrami. 2011. “Man Evolution: An Islamic Point of View.” European Journal of Science and Theology 7(3), 17–28.
15. Goodman, Lenn E., and Richard McGregor. 2012. The Case of Animals Versus Man: Before the King of the Jinn – A Translation from the Epistles of the Brethren of Purity. Oxford: Oxford University Press.
16. Guessoum, Nidhal. 2011. Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. London: I.B. Tauris.
17. Hakim, Khalifa Abdul. 1959. The Metaphysics of Rumi: A Critical and Historical Approach. Lahore: The Institute of Islamic Culture.
18. Hamad, Mawieh. 2007. “Islamic Roots to the Theory of Evolution: The Ignored History.” Rivista di Biologia, 100(2): 173–178.
19. Hameed, Salman. 2011. “Evolution and Creationism in the Islamic World.” In Thomas Dixon, Geoffrey Cantor, and Stephen Pumfrey, eds. Science and Religion: New Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 133–154.
20. Hameed, Salman. 2014. “Evolution of Species, Islamic Ideas.” In Amils R. et al. eds. Encyclopedia of Astrobiology. Berlin: Springer.
21. Ibn Khaldūn, Abū Zayd ʿAbd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad. 2005. The Muqaddimah. trans. by Franz Rosenthal. New Jersey, NY: Princeton University Press.
22. Iqbal, Muzaffar. 2003.“Biological Origins: Traditional and Contemporary Perspectives.” Islamic Herald. Accessed 1st of October 2019. Available at: http://saif_ w.tripod.com/curious/evolution/muz/biological_origins.htm.
23. Iqbal, Muhammad. 2012. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bhavan.
24. Kartenegara, Mulyadhi. 2016. “Rumi on the Living Earth: A Sufi Perspective.” In Mohammad Hashim Kamali, Osman Bakar, Dauf Abul-Fattah Batchelor, and Rugayah Hashim, eds. Islamic Perspectives on Science and Technology: Selected Conference Papers. Singapore: Springer.
25. Kaya, Veysel. 2011. “Can the Quran Support Darwin? An Evolutionist Approach by Two Turkish Scholars after the Foundation of the Turkish Republic.” The Muslim World, 102: 357–370.
26. Kruk, Remke. 1995. “Traditional Islamic Views of Apes and Monkeys.” In Frank Spencer, Raymond Corbey, and Bert Theunissen, eds. Ape, Man, Apeman: Changing Views Since 1600. Leiden: Leiden University.
27. Lovejoy, Arthur Oncken. 2009. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. New Jersey, NY: Transaction Publishers.
28. Malik, Amina H., Janine M. Ziermann, and Rui Diogo. 2017. “An Untold Story in Biology: The Historical Continuity of Evolutionary Ideas of Muslim Scholars From the 8th Century to Darwin’s Time.” Journal of Biological Education, 52(1): 1–15.
29. Mansūr, Saʿīd H. 1977. The Worldview of al-Jāḥiẓ in Kitāb al-Ḥayawān. Alexandria: Dār al-Maʿārif.
30. Mojaddedi, Jawid. 2017. The Masnavi: Book Four. Oxford: Oxford University Press.
31. Montgomery, James E. 2013. Al-Jāḥiẓ: In Praise of Books. Edinburgh: Edinburgh University Press.
32. Morewidge, Parviz. 1992. “The Neoplatonic Structure of Some Islamic Mystical Doctrines.” In Parviz Morewedge, ed. Neoplatonism in Islamic Thought. Albany, NY: State University of New York Press.
33. Nasr, Seyyed Hossein. 1978. An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Bath: The Pitman Press.
34. Netton, Ian R. 1991. Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of the Brethren of Purity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
35. Netton, Ian R. 2003. “The Brethren of Purity (Ikhwān Al-Ṣafā).” In Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, eds. The History of Islamic Philosophy. New York, NY: Routledge.
36. Pollock, Sheldon. 2009. “Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard World.” Critical Inquiry, 35(4): 931–961.
37. Principe, Lawrence M. 2016. “Scientism and Religion of Science.” In Richard N. Williams and Daniel N. Robinson, eds. Scientism: The New Orthodoxy. London: Bloomsbury, 41–62.
38. Rūmī, Jalāl ad-Dīn. 2003. The Mathnawi. Volume IV. trans. by Reynold A. Nicholson. Karachi: Darul Ishaat.
39. Russel, Colin A. 2002. “Conflict of Science and Religion.” In Gary B. Ferngren, ed. Science and Religion: A Historical Introduction. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 3–12.
40. Shah, Muhammad Sultan. 2010. Evolution and Creation: Islamic Perspective. Mansehra: Society for Interaction of Religion, Science and Technology.
41. Shanavas, T. O. 2010. Islamic Theory of Evolution: The Missing Link between Darwin and the Origin of Species. USA: Brainbow Press.
42. Stearns, Stephen C., and Rolf F. Hoekstra. 2005. Evolution: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. Stott, Rebecca. 2012. Darwin’s Ghost’s: The Secret History of Evolution. New York, NY: Spiegel and Grau.
43. Twetten, David. 2017. “Arabic Cosmology and the Physics of Cosmic Motion.” In Richard C. Taylo, and Luis Xavier López-Farjeat, eds. The Routledge Companion to Islamic Philosophy. Abingdon: Routledge, 156–167.
44. Ungureanu, James C. 2019. Science, Religion, and the Protestant Tradition: Retracting the Origins of the Conflict. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
45. Wehr, Hans, and Cowan, J. Milton. 1976. A Dictionary of Modern Written Arabic. New York: Spoken Language Services, Inc.
46. Wilczynski, Jan Z. 1959. “On the Presumed Darwinism of Alberuni Eight Hundred Years Before Darwin.” History of Science Society, 50(4): 459–466.
47. Wildberg, Christian. 2016. “Neoplatonism.” The Stanford Encyclopaedia of Philosophy. Accessed 3rd of November 2020. Available at: https://plato.stanford. edu/archives/spr2016/entries/neoplatonism/.