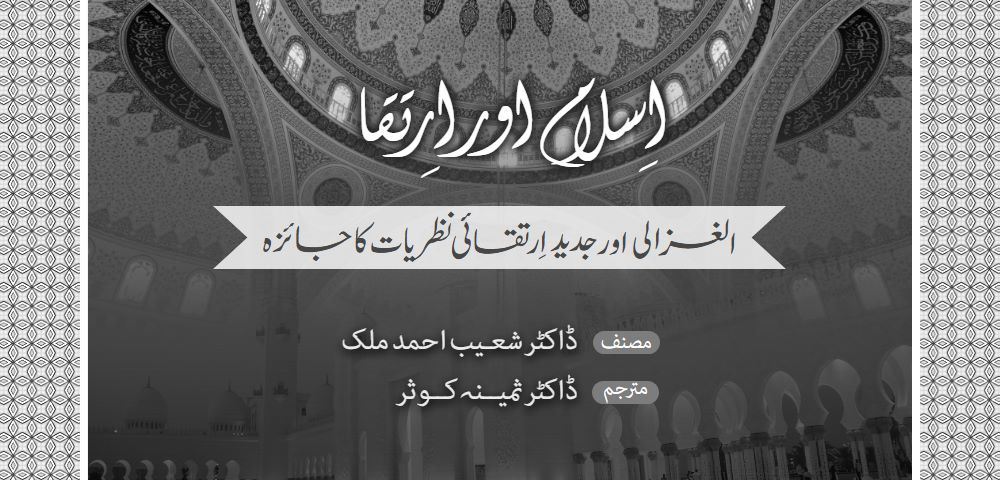مسلم فکر اور نظریہ ارتقا
تعارف
گذشتہ صفحات میں ہم نے عیسائی سیاق و سباق میں نظریہ ارتقا سے متعلق چار اہم موضوعات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد باب 3 میں، ہم نے اسلامی صحیفے کا مطالعہ کیا، جہاں ارتقا سے متعلق مختلف قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر عیسائی مفکرین اور مذہبی گروہوں کے مؤقف کا اسلامی تناظر میں موازنہ اور تجزیہ کیا گیا۔ اس تجزیے کے دوران کچھ ایسے نکات بھی سامنے آئے جو اسلامی تناظر کے باوجود، عیسائی سیاق کے لیے زیادہ موزوں یا اہم دکھائی دیے۔ یہاں ہم اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ان مسلم مفکرین کے دلائل کا جائزہ لیں گے جنہوں نے اسلام اور نظریہ ارتقا کے مابین مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس بحث کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مختلف درجہ بندیوں (classification schemes) کو بھی سمجھیں، جو اس موضوع کو منظم انداز میں سمجھنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔ یقیناً ہر درجہ بندی کسی مخصوص زاویے کو مدنظر رکھتے ہوئے تشکیل دی جاتی ہے، جس کے ذریعے مصنف یا محقق وہ نکات اجاگر کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی موجود رہتا ہے کہ یہ درجہ بندیاں کسی اور سیاق و سباق میں ، بالخصوص مسلم فکری روایت پر پوری طرح لاگو نہ ہو سکیں۔ مثلاً بعض درجہ بندیاں امریکہ یا مغرب کے مخصوص فکری ماحول کے لیے بہت موزوں ہیں، مگر وہ مسلم تناظر میں قدرے غیر فطری یا غیر متعلق محسوس ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس باب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پہلا حصہ ان مختلف درجہ بندیوں اور فریم ورکس کا تنقیدی جائزہ پیش کرتا ہے جو ارتقا اور مذہب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ ان درجہ بندیوں پر کی جانے والی تنقیدات کیا ہیں، اور ان میں سے کون سا فریم ورک زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہم ایک مخصوص درجہ بندی کو اختیار کریں گے جو صرف اور صرف مشترکہ نسب (common ancestry) کے مسئلے پر مرکوز ہے، وہیں اس انتخاب کی عقلی توجیہ بھی بیان کی جائے گی۔ دوسرا حصہ اسی منتخب درجہ بندی کو مسلم مفکرین کے بیانات، افکار اور تحریروں پر لاگو کرے گا۔ اس حصے میں ایک جامع جدول (summary table) بھی شامل کیا جائے گا جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ ہر مفکر مشترکہ نسب کے تصور سے کس حد تک اتفاق یا اختلاف کرتا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔
درجہ بندیوں کا جائزہ
اسلام اور ارتقا کے حوالے سے لوگوں کی آرا کو کس طرح ترتیب دیا جائے اور ان کی درجہ بندی کیسے جائے ؟ یہ ایک نہایت پیچیدہ اور محنت طلب کام ہے۔ جیسا کہ ہم باب اول میں دیکھ چکے ہیں، ارتقا ایک کثیرالمضامین (multipropositional) نظریہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ارتقا کو بیان کرنے کے لیے کئی پہلو بیک وقت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں "طویل زمانی تسلسل" (deep time) اور "مشترکہ نسب" (common ancestry) شامل ہیں، جبکہ بے ترتیب تغیرات (random mutation) اور قدرتی انتخاب (natural selection) جیسے عوامل اسے نیو ڈارونیت (Neo-Darwinism) کی شکل دیتے ہیں۔ اسی لیے جب لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ "ارتقا" پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ سوال ایک مجموعی اور مبہم انداز میں کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جواب صرف دو میں سے ایک ہو سکتا ہے یعنی ہاں یا ناں ، حالانکہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں جان پاتے کہ وہ اصل میں ارتقا کے کس پہلو کو قبول یا رد کر رہے ہیں۔ کیا وہ طویل زمانی عمل (یعنی زمین اور زندگی کی قدیم تاریخ) کو نہیں مانتے؟ یا مشترکہ نسب (یعنی تمام جانداروں کا ایک ہی جد امجد ہونا) کو؟ یا پھر وہ ارتقا کے سائنسی طریقۂ کار جیسے بے ترتیب تغیر اور قدرتی انتخاب کو مسترد کر رہے ہیں؟ یا شاید وہ ان تمام باتوں کو ایک ساتھ رد کر رہے ہیں؟ اگر "ارتقا" کو ایک ہی جامع اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے تو ان مختلف اور اہم اجزاء میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بحث مبہم ہو جاتی ہے۔
اس مسئلے کے علاوہ ایک اور پیچیدگی مفاہیم (connotations) سے متعلق ہے۔ "ارتقا" اور "(نیو)ڈارونیت" بعض سیاق و سباق میں ایسے بھاری بھرکم مفہوم کی حامل اصطلاحات بن چکی ہیں کہ وہ سننے والے کے ذہن میں فوراً الحاد، مادہ پرستی اور فطرت پرستی جیسے تصورات کو جنم دیتی ہیں ۔ حالانکہ یہ تصورات منطقی طور پر ارتقا سے لازم و ملزوم نہیں۔ یعنی، ارتقا پر یقین رکھنے کا لازمی مطلب الحاد یا مادہ پرستی نہیں ہے۔ تاہم تاریخی اور سماجی حوالوں سے ارتقا کو تھیزم بمقابلہ الحاد کی بحث میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ "ارتقا" یا "ڈارونیت" جیسی اصطلاحات اپنی غیر جانب داری کھو چکی ہیں۔ مشہور نیو ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاکنز جیسے مفکرین ارتقا اور الحاد کو ہم معنی بنا کر پیش کرتے ہیں، اسی لیے وہ پرزور انداز میں کہتے ہیں کہ آدمی یا تو مومن ہو سکتا ہے یا ارتقائی مفکر (believer or evolutionist)، درمیانی راستہ کوئی نہیں(Elsdon-Baker 2009; 2017) ۔ یہی زبان، یہی اندازِ استدلال، اور یہی سادہ ثنویت (binarism) اس اہم علمی بحث کو غیر ضروری الجھاؤ کا شکار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح عوامی سطح پر سائنسی اصطلاحات کے عمومی فہم میں بھی الجھن پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم باب اول میں دیکھ چکے ہیں،جیسے "نظریہ" (theory) کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو روزمرہ بول چال میں لیا جاتا ہے۔ لیکن عام لوگ اس فرق سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور یوں "نظریہ ارتقا" کو محض ایک قیاس یا غیر مصدقہ رائے سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔
ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے ہاں ارتقا سے متعلق سروے اور شماریاتی ڈیٹا کو بہت محتاط انداز میں پڑھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ریاض حسن (2007) نے متعدد مسلم اکثریتی ممالک میں ایک جامع سروے کیا، جن میں مصر، قازقستان، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی اور ملائیشیا شامل تھے۔ اس سروے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا "کیا آپ ڈارون کے نظریہ ارتقا سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟" کارلائل وغیرہ (2019: 152) نے اس سوال پر تنقید کرتے ہوئے بجا طور پر درج ذیل نکات اٹھائے:
یہ سوال کئی حوالوں سے مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اول، یہ فرض کرتا ہے کہ جواب دینے والے کو ڈارونیت کی تفصیلات کا علم ہے۔ دوم، اس میں 'نظریہ' کا لفظ استعمال ہوا ہے، جسے عام لوگ شک یا غیر یقینی کے مفہوم میں لیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ سائنسی برادری میں ارتقا کتنی اچھی طرح سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ سوم، یہ سوال ایک جدید تحقیقی شعبے کو صرف ڈارون سے منسوب کرکے ایک تاریخی شخصیت سے جوڑ دیتا ہے، جس سے ارتقا کا سائنسی تصور مغربی استعماری مادہ پرستی کی علامت بن جاتا ہے۔ آخر میں، یہ سوال انسانی اور غیر انسانی ارتقا کے درمیان فرق نہیں کرتا Carlisle et al. (2019, 152) ۔
کارلائل وغیرہ کی یہ آخری تنقید خاص طور پر قابلِ غور ہے، کیونکہ بعض مسلم مفکرین انسانی ارتقا اور غیر انسانی (یعنی جانوروں و نباتات) ارتقا میں فرق کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس فرق سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ پورے ارتقائی نظریے کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہمیں Pew World Muslim Poll (2013) میں نظر آتا ہے، جس میں درج ذیل سوال اور جوابی اختیارات دیے گئے تھے:
ارتقا کے بارے میں سوچتے ہوئے، درج ذیل میں سے کون سا جواب آپ کے خیال سے زیادہ قریب ہے؟
- انسان اور دیگر جاندار وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی عمل سے گزرے ہیں
- انسان اور دیگر جاندار ابتداء سے اپنی موجودہ شکل میں موجود ہیں
- معلوم نہیں
ایلزڈن بیکر (2015) نے اس سوال کو بھی مسئلہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا فریم امریکی ماحول سے شدید متاثر ہے، جہاں " سب کچھ مانو یا کچھ بھی نہیں" کا رجحان پایا جاتا ہے(Elsdon-Baker 2015, 434)۔ وہ بجا طور پر اس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ ہمارے سروے کے انداز اور سوالات کا طریقہ خود بخود ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے جو تخلیق پرستی (creationism) کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
چنانچہ انسانی اور غیر انسانی ارتقا کے درمیان فرق کرنا اس بحث کو زیادہ مؤثر اور متوازن بنا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ارتقا کو مکمل طور پر رد کرنے کے بجائے جزوی طور پر قبول کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔
مثال کے طور پر Unsworth and Voas (2018) نے اپنے سروے میں ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ پرکھا۔ انہوں نے 815 مسلمانوں پر مشتمل نمونے کے ذریعے مختلف مذہبی گروہوں کے ردعمل کا جائزہ لیا۔ ان کے نتائج سے پتا چلا کہ جب غیر انسانی ارتقا (یعنی پودوں اور جانوروں کی ارتقائی تبدیلی) کی بات کی گئی تو 42.4فیصد شرکا نے اس سے مضبوط اتفاق ظاہر کیا، جبکہ صرف 26.2 فیصد نے اس سے سخت اختلاف کیا۔ باقی شرکا نے کوئی واضح رائے نہیں دی۔ دوسری جانب، جب سوال انسانی ارتقا سے متعلق تھا تو صرف26.9 فیصد شرکا نے اس کی حمایت کی، جبکہ44.2 فیصد نے اس سے واضح اختلاف کیا۔ باقی شرکا غیر جانب دار رہے۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسانی اور غیر انسانی ارتقا کے درمیان فرق کرنا نہایت اہم ہے، اور اس فرق کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی درست یا متوازن رائے قائم کرنا مشکل ہو سکتا ہے (also see Elsdon-Baker et al. 2017)۔
ایلزڈن بیکر کی یہ بات بھی وضاحت طلب ہے کہ کس طرح بعض چیزوں کو امریکی ماحول میں ایک خاص انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے باب2 اور3 میں دیکھ چکے ہیں، کچھ موضوعات بعض عیسائی حلقوں میں مسلم حلقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ حساسیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایسی درجہ بندی اپنائیں جو ان حساسیتوں کو ایک سیاق و سباق سے اٹھا کر کسی دوسرے سیاق میں جوں کا توں منتقل کر دے، تو یہ طریقہ کار زیادہ مفید نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر، Eugenie Scott (2002) کی جانب سے پیش کردہ درجہ بندی کو دیکھیں، جو مختلف آرا کے ایک تسلسل پر مبنی ہے اور امریکی سیاق میں موجود مذہبی اور سائنسی حساسیتوں کو مدنظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہے۔
اصل کتاب کے صفحہ 109 پر موجود Table 4.1 کو دیکھیں تو اس کے بالائی اور نچلی سطحیں آرا کے ایک تسلسل کے دو انتہاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ Eugenie Scott اس درجہ بندی کا آغاز اُن لوگوں سے کرتی ہیں جو زمین کو بالکل چپٹی (flat earth) مانتے ہیں، اور اس کا اختتام مکمل مادیاتی ارتقا (materialist evolution) پر ہوتا ہے، جس کا مطلب خدا کے تصور کا انکار ہوتا ہے۔ یہ درجہ بندی امریکی تناظر میں شاید موزوں ہو، جہاں بعض مذہبی گروہ سائنسی علم کے پورے دائرے کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ Scott نے اس تسلسل میں flat earthers (زمین کو چپٹا ماننے والے) اور geocentrists (زمین کو کائنات کا مرکز ماننے والے) جیسے گروہوں کو بھی شامل کیا۔ مگر یہ سوچنا کہ یہی درجہ بندی مسلم دنیا پر بھی اسی طرح لاگو کی جا سکتی ہے، ایک محتاط جائزے کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم دنیا میں flat earthers یا geocentrists موجود ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ پائے جاتے ہوں۔ 2017 میں تیونس کی ایک طالبہ نے ایک تھیسس جمع کروایا جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ زمین کی عمر صرف 13ہزار پانچ سو سال ہے، یہ ساکن ہے اور کائنات کا مرکز بھی ہے (Guessoum 2017)۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ صرف ایک انفرادی کیس ہے یا پھر ایک وسیع تر رجحان؟ اس کا تعین کیے بغیر مسلم تناظر میں ایسی درجہ بندی کو اپنانا قبل از وقت ہوگا۔ Unsworth and Voas (2018, 82) کی تحقیق کی طرف واپس آئیں تو ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ50 فیصد مسلمان شرکا نے اس بات سے واضح اتفاق کیا کہ زمین کی عمر اربوں سال ہے، جبکہ صرف5.5فیصد نے اس سے سخت اختلاف کیا (باقی شرکا غیر جانبدار رہے)۔ یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید مسلم دنیا میں زمین کو چپٹا ماننے کا رجحان زیادہ عام یا فکری مسئلہ نہیں ہےمگر یہ بات بھی صرف احتیاط کے ساتھ ہی کہی جا سکتی ہے۔
اس درجہ بندی کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سائنسی عقائد کو خدا پر ایمان یا انکار سے مربوط کر کے یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس تسلسل (spectrum) میں ایک طرف وہ مقام ہے جہاں سائنسی اور مذہبی عقائد سے کم از کم مطابقت پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ مقام ہے جہاں سائنسی نظریات سے مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی خدا کے وجود کا انکار بھی کیا جاتا ہے (Huskinson 2020, 9)۔ اس درجہ بندی میں موجود یہ دہرا میلان دراصل اسی "دو انتہاؤں کی طرف کھینچنے والے رجحان" (bifurcation tendency) کو نمایاں کرتا ہے جس کی طرف پہلے رچرڈ ڈاکنز کے تناظر میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس درجہ بندی سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سائنسی سوچ رکھتا ہے تو اسے لازماً خدا کے وجود کا انکار کرنا ہو گا، جو کہ ایک غیر ضروری اور غیر منطقی تصور ہے۔
ان مشاہدات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی ایک مخصوص سماجی یا فکری سیاق میں تیار کی گئی درجہ بندی کو کسی دوسرے تناظر پر لاگو کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر، یہ درجہ بندیاں غلط فہمی، فکری الجھن اور غیر موزوں نتائج کا سبب بن سکتی ہیں۔
کچھ مسلم مفکرین جنہوں نے اسلام اور نظریہ ارتقا کے مابین ہونے والی علمی بحث کا جائزہ لیا ہے، انہوں نے اس موضوع کو مختلف انداز میں درجہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ جسّوم (Guessoum, 2016) نے اس کے لیے ایک تین سطحی درجہ بندی اپنائی، جس میں وہ افراد شامل ہیں جو ارتقا کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں (rejectionists)، وہ جو درمیانی یا معتدل رائے رکھتے ہیں (moderates)، اور وہ جو ارتقا کے حامی ہیں (pro-evolutionists)۔ مالک (Malik 2018; 2019) نے جسّوم کی درجہ بندی کو اختیار کرتے ہوئے ملتا جلتا خاکہ پیش کیا، لیکن انہوں نے اصطلاحات میں قدرے تبدیلی کی۔ وہ "رد" (rejection)، "موافقت" (accommodative)، اور "قبولیت" (acceptance) کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ مالک اور جسّوم کی درجہ بندی میں Eugenie Scott کے ماڈل کے مقابلے میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ارتقا کو قبول کرنے کے لیے خدا کے انکار کی شرط نہیں ہے۔ یہ تصور خاص طور پر مسلم تناظر میں زیادہ معقول محسوس ہوتا ہے۔ اس درجہ بندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر گروہ (خیمہ) میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، بعض مفکرین جو ارتقا کو مکمل طور پر قبول یا رد کرتے ہیں، ان کے دلائل سائنسی بھی ہو سکتے ہیں، الہیاتی (theological) بھی، یا پھر تفسیری اصولوں (hermeneutic) پر مبنی بھی یا ان سب کا مجموعہ۔ چنانچہ جسّوم اور مالک کا اندازِ درجہ بندی ان مختلف جہات کو سنبھالنے میں مدد دیتا ہے۔
البتہ اس اسکیم میں ایک کمزوری یہ ہے کہ کسی مفکر کے مؤقف کو قبول یا رد کے زمرے میں شامل کرنا دراصل اس شخص کی اپنی رائے نہیں بلکہ درجہ بندی کرنے والے کی تشریح پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جسّوم اور مالک دونوں ڈیوڈ سولومن جلاجیل (David Solomon Jalajel) کو "رد کرنے والوں" کے زمرے میں رکھتے ہیں (Guessoum 2016; Malik 2019, 210)، حالانکہ خود جلاجیل (2018) اپنے مؤقف کو ارتقا سے مکمل طور پر ہم آہنگ سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات درجہ بندی کرنے والے کی تشریح اور اصل مفکر کی خود فہمی میں تضاد ہو سکتا ہے۔ اس درجہ بندی کا ایک اور ممکنہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت وسیع اصطلاحات پر مشتمل ہے، اس لیے بعض اوقات مختلف آرا کا تقابلی مطالعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتفاق یا اختلاف کی وجوہات کئی پہلوؤں سے پیدا ہو سکتی ہیں — جیسے سائنسی تشخیص، ما بعد الطبیعی اصول (metaphysical principles)، یا تفسیر سے متعلق وابستگیاں۔ لہٰذا ان اختلافات یا اتفاقات کو کسی ایک مشترک بنیاد پر پرکھنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔
اس عنوان پر موجود علمی ذخیرے میں ایک اور اہم درجہ بندی غفوری فرد اور محمد اکرمی (2011) کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ ان کی درجہ بندی چار اقسام پر مشتمل ہے، اور اس کا بنیادی محور قرآن و سنت اور سائنسی علم کے درمیان تعلق ہے۔ پہلا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ارتقا محض ایک "نظریہ" ہے، لیکن انسان کی تخلیق کو ایسے انداز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس سے وہ ارتقا کے تصور سے ہم آہنگ ہو جائے۔ دوسرا گروہ یہ مؤقف رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کے متون بالکل واضح ہیں اور انسان کی تخلیق کی تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا اگر ارتقا درست بھی ہو، تب بھی انسان اس سے مستثنیٰ ہے۔تیسرا گروہ یہ خیال رکھتا ہے کہ قرآن اور سائنس بالکل مختلف دائروں میں کام کرتے ہیں، یعنی ان کا باہمی تعلق یا براہِ راست مکالمہ ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک قرآن سائنسی کتاب نہیں، اس لیے سائنسی نظریات پر ایمان رکھنا یا نہ رکھنا غیر متعلق ہے۔ چوتھا گروہ یہ مؤقف اختیار کرتا ہے کہ انسانی ارتقا کو براہِ راست قرآن سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ گروہ سائنس کی صحت اور اسلامی متن سے انسانی ارتقا کی قطعی تعبیر کا قائل ہے۔ اس گروہ اور پہلے گروہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ ارتقا کو ممکن بنانے کے امکانات پر زور دیتا ہے، جبکہ چوتھا گروہ اسے یقینی حقیقت کے طور پر مانتا ہے۔
اگرچہ یہ درجہ بندی خاص طور پر انسانی ارتقا پر مرکوز ہے، مگر اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف فکری وابستگیوں (epistemic commitments)، تفسیری رجحانات (hermeneutic commitments)، اور سائنس و وحی کے باہمی تعلق کو ایک ہی سانچے میں سمو دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض علمی یا فکری موقف محض درجہ بندی کی نوعیت کے باعث ایک دوسرے سے غیر ضروری طور پر مختلف نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ صرف شدت یا درجے میں مختلف ہوتے ہیں، نوعیت میں نہیں۔
مثال کے طور پر، پہلا اور چوتھا گروہ بظاہر ایک ہی سمت میں سوچتے ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق محض یقین کی شدت کا ہے، نہ کہ بنیادی موقف کا۔ اس درجہ بندی میں ایک اور کمی یہ ہے کہ وہ اُن افراد کو شامل نہیں کرتی جو صرف ایک پہلو (مثلاً صرف سائنسی دلیل) کی بنیاد پر ارتقا کو قبول یا رد کرتے ہیں، اور دینی متون پر کوئی واضح رائے نہیں رکھتے۔ یعنی ایک فرد صرف اس بنیاد پر ارتقا کو مسترد کرتا ہے کہ موجودہ سائنسی دلائل اسے قائل نہیں کرتے، لیکن وہ دینی متون سے متعلق کوئی مؤقف نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کو اس درجہ بندی میں کسی واضح خانے میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
آخر میں، خود مصنفین کے مطابق، کچھ مفکرین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ارتقا کو سائنس یا دینی دلائل کے بجائے کسی ما بعد الطبیعیاتی نقطہ نظر سے قبول یا رد کرتے ہیں۔ سید حسین نصر اس کی ایک واضح مثال ہیں، جن کے ہاں ارتقا کو رد کرنے کی بنیادی وجہ ان کا وہ روحانی ما بعد الطبیعیاتی وژن ہے جس میں ارتقا کا کوئی وجود ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک سائنس یا تفسیر کی بحث ثانوی ہے، جس کے باعث ان کے مؤقف کو اس درجہ بندی میں رکھنا مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔
یقیناً، ہر درجہ بندی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ درجہ بندی کرنے والا کس پہلو کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ جسّوم (2016) اور مالک (2018؛ 2019) کے ہاں یہ جھکاؤ واضح نظر آتا ہے کہ وہ ایک وسیع اور جامع درجہ بندی اختیار کرتے ہیں جو علمی ادب میں موجود مختلف آرا کو سمیٹ سکے، بالخصوص ان کے درمیان مطابقت یا عدم مطابقت پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس غفوری فرد اور محمد اکرمی (2011) کی درجہ بندی کا محور زیادہ تر سائنس اور وحی کے باہمی تعلق پر مرکوز ہے۔ ہر نظام درجہ بندی کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی۔ اس کتاب میں جو درجہ بندی اختیار کی گئی ہے، وہ نہ صرف مذکورہ دونوں نظاموں میں بیان کردہ مسائل کو سنجیدگی سے لیتی ہے بلکہ پہلے بیان کیے گئے دیگر نکات کو بھی مدنظر رکھتی ہے۔ اس درجہ بندی کو وضع کرنے میں تین بنیادی اصول رہنمائی کرتے ہیں:
پہلا اصول:
مرکزی بنیاد کے طور پر مشترکہ نسب (common ancestry) پر توجہ مرکوز کرنا۔
چونکہ اصل بحث کا مرکز انسانی ارتقا ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مشترکہ نسب کو درجہ بندی کا واحد اور اساسی معیار بنایا جائے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو مختلف مفکرین کے موقف کو ایک واضح معیار پر جانچنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
دوسرااصول:
اس بات کو الگ کرنا کہ کوئی شخص ارتقا کو کیوں قبول یا مسترد کرتا ہے، اور وہ ارتقا کے کن اجزا کو مشترکہ نسب کے تحت مانتا یا نہیں مانتا۔
چونکہ مختلف مفکرین ارتقا کو سائنسی، مابعد الطبیعیاتی (metaphysical)، یا تفسیری (hermeneutic) زاویوں سے قبول یا رد کرتے ہیں، اس لیے ان کے اسباب کو خود درجہ بندی سے الگ رکھنا زیادہ مفید سمجھا گیا۔ اس سے درجہ بندی سادہ، قابلِ فہم اور موازنہ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔
تیسرااصول:
مطابقت پذیری (reconciliation) کے سوال کو درجہ بندی سے الگ رکھنا۔ یہ اصول دوسرے اصول سے ملتا جلتا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک الگ نکتہ ہے۔ ارتقا پر ایمان رکھنا ایک بات ہے، اور اسے اپنے دینی عقائد سے ہم آہنگ کرنا (یا نہ کرنا) ایک اور بات۔ اس اصول کو اختیار کرنے سے اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے جس میں درجہ بندی کرنے والے اور متعلقہ مفکر کے ذاتی موقف کے درمیان فہم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر واضح کیا جائے گا کہ یہ نکتہ کس طرح اہم ثابت ہوتا ہے۔
مندرجہ بالا اصولوں کی روشنی میں اصل کتاب کے صفحہ 111 پر موجود Table 4.2 میں ایک نئی درجہ بندی کا نظام پیش کیا گیا ہے، جو زیادہ منظم، سادہ، اور فکری تنوع کو بہتر طور پر سنبھالنے کے قابل ہے۔
مشترکہ نسب (common ancestry) میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں، اس کا خلاصہ تین بنیادی زمروں میں کیا جا سکتا ہے: غیر انسانی مخلوقات، انسان، اور آدم علیہ السلام۔ سادگی کے لیے "آدمی استثنائیت" (Adamic exceptionalism) کے تحت حضرت حوّا کو بھی حضرت آدم کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کو معجزاتی طور پر پیدا شدہ مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی مفکر یہ مؤقف رکھتا ہے کہ ہر مخلوق ارتقائی عمل سے خارج ہے، یعنی کوئی بھی ارتقا کا حصہ نہیں، تو اسے تخلیقیت (Creationism) کہا جاتا ہے۔ انسانی استثنائیت (Human Exceptionalism) کا مطلب یہ ہے کہ غیر انسانی مخلوقات (مثلاً جانور، پودے وغیرہ) کے ارتقا کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن حضرت آدم (جنہیں اس تناظر میں پہلا انسان مانا جاتا ہے) اور پوری انسانیت کو ارتقا کا نتیجہ نہیں سمجھا جاتا۔ آدمی استثنائیت (Adamic Exceptionalism) کا مطلب یہ ہے کہ غیر انسانی مخلوقات اور انسان دونوں ارتقا کے ذریعے وجود میں آئے، لیکن صرف حضرت آدم ارتقائی عمل سے مستثنیٰ ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت آدم کو پہلا انسان نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ ایک معجزاتی استثناء تھے۔ آخر میں، بلا استثنا مؤقف (No Exceptions) وہ نظریہ ہے جس میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ارتقائی عمل سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ یعنی غیر انسانی مخلوقات، انسان اور حضرت آدم سب ارتقائی عمل کے تحت وجود میں آئے ہیں۔
(جاری)