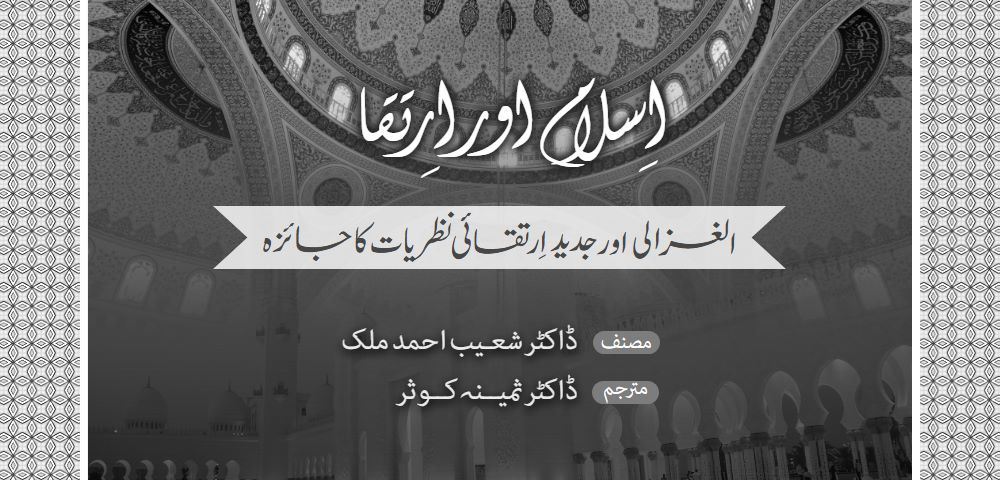انسانی امتیاز
(Human Exceptionalism)
جدول 4.3 میں ہم نے تین مختلف مفکرین کا ذکر کیا ہے جو انسانی امتیاز (Human Exceptionalism) کے قائل ہیں۔ نوح میم کیلر (Nuh Ha Mim Keller)، یاسر قاضی اور نذیر خان ۔ بعد کے دونوں مصنفین نے اس موضوع پر ایک مشترکہ مقالہ بھی تحریر کیا ہے، اس لیے یہاں ہم تینوں مصنفین کی دو تحریروں کا جائزہ لیں گے جو انسانی امتیاز کے حق میں ہیں۔ ابتدا ہم کیلر سے کرتے ہیں۔
1995 میں، سلیمان علی نامی ایک ماہرِ حیاتیات ایک پمفلٹ پڑھ کر متأثر ہوئے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ارتقا شرک کے مترادف ہے۔ (شرک سے مراد اللہ کے ساتھ کسی اور کو الوہیت میں شریک کرنا ہے، جیسے بت پرستی، جو اسلامی فکر میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔) اس صورتحال میں انہوں نے ایک فیکس نوح میم کیلر کو بھیجا، جو ایک مسلمان متکلم ہیں، اور ان سے اسلام اور ارتقا کے بارے میں اپنی رائے دریافت کی (Keller 2011, 350)۔ اسی سوال کے جواب میں کیلر نے ارتقا پر اپنی تنقید پیش کی۔
کیلر نے ارتقا پر کئی اعتراضات کیے ہیں، مگر سہولت کے لیے انہیں تین بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اعتراض سائنس کے حوالے سے ہے۔ کیلر تسلیم کرتے ہیں کہ ایک وقت میں انہیں لگا کہ ارتقا ناقابلِ رد ہے، لیکن چارلس ڈارون کی کتاب On the Origin of Species پڑھنے کے بعد ان کی رائے بدل گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو نکات اٹھائے۔ ان کا پہلا اعتراض ارتقا کے نظریے کی قابلِ ابطالیت (falsifiability) پر ہے (Keller 2011, 351–352):
ڈارون کی کتاب کا نواں باب … جسے ڈارون نے نہایت عاجزی کے ساتھ ‘the great imperfection of the geological record’ کہا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ نظریہ اصولی طور پر قابلِ ابطال (falsifiable) نہیں تھا۔ حالانکہ ماہرین منطق جیسے کارل پوپر (Karl Popper) کے مطابق کسی نظریے کے سائنسی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اصولی طور پر کوئی نہ کوئی شہادت اسے غلط ثابت کر سکے۔ لیکن فطری طور پر ایسے فوسلز جو درمیانی انواع (intermediate forms) کو ثابت یا رد کر سکیں، نہ تو ملے ہیں اور نہ ہی مل سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ ایسے نظریے کو 'سائنسی' کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اگر ارتقا سائنسی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ ایک انسانی تعبیر ہے، ایک کاوش، ایک صنعت، ایک لٹریچر، جو دراصل اس طریقہ استدلال پر قائم ہے جسے امریکی فلسفی چارلس پیئرس (Charles Peirce) نے abductive reasoning کہا ہے، یہ طرزِ استدلال درج ذیل طریقے سے کام کرتا ہے:
1. ایک حیران کن حقیقت A سامنے آتی ہے۔
2. اگر نظریہ B درست ہو تو A فطری طور پر اس کے نتیجے میں سمجھ میں آتی ہے۔
3. لہٰذا B درست ہے۔
یہاں (1) بالکل یقینی ہے، (2) محض محتمل ہے (کیونکہ یہ حقائق کو بیان کرتا ہے، مگر دوسرے ممکنہ نظریات کو خارج نہیں کرتا)، جبکہ (3) کی صداقت صرف اتنی ہی ہے جتنی (2) کی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے ارتقا کا مقدمہ کتنا مضبوط ہے تو اب تک دریافت ہونے والے تمام فوسلز کی ایک فہرست بنائیں جنہیں 'انسان کے ارتقا' کا ثبوت کہا جاتا ہے، ان کی تاریخیں نوٹ کریں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہی abductive reasoning ہے جو اس نظریے کو آگے بڑھاتی ہے؟ اور کیا یہ امکان رد کر دیتی ہے کہ نظریہ ارتقا کی جگہ پر بالکل مختلف (2) پیش کی جا سکتی ہے؟
اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیلر کے نزدیک ارتقا ایک ہمہ گیر نظریہ ہے جس کے اندر کوئی داخلی معیارِ ابطال (internal falsification criteria) موجود دکھائی نہیں دیتا۔ کارل پوپر کا حوالہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیلر کے ذہن میں غالباً سگمنڈ فرائڈ اور الفریڈ ایڈلر کے نفسیاتی نظریات ہیں، جو کسی بھی قسم کے ڈیٹا کی وضاحت کر سکتے تھے کیونکہ وہ حد سے زیادہ وسیع اور مبہم تھے (Popper 2002a, 43–77)۔ ان دونوں یعنی فرائڈ اور ایڈلر کے نظریات کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ پوپر نے اپنے مشہور "معیارِ ابطال" (falsification criterion) کو سائنسی اور غیر سائنسی نظریات کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لیے وضع کرتے وقت انہی نظریات کا تقابل زیادہ مضبوط سائنسی نظریات، مثلاً آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت، کے ساتھ کیا تھا (Popper 2002b, 57–73)، یہ بحث باب اوّل میں کی جا چکی ہے۔
کیلر کا دوسرا سائنسی اعتراض ارتقا پر بڑی ارتقائی تبدیلی (macroevolution) کے ثبوت کی کمی سے متعلق ہے۔ خطیبانہ انداز میں وہ اپنے شکوک اس طرح بیان کرتے ہیں (Keller 2011, 352):
کیا ایک نوع (species) کے اندر ہونے والی چھوٹی ارتقائی تبدیلیوں (micro-evolution) کی مثالیں، جو گھوڑوں اور کبوتروں کی افزائش، یا مفید پودوں کی نئی اقسام کے ذریعے کافی حد تک ثابت ہوتی ہیں، واقعی macro-evolution یعنی ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیلی کے لیے بھی قابلِ اطلاق ہیں؟ کیا اس بات کی کوئی ایک بھی مثال موجود ہے کہ ایک نوع حقیقتاً دوسری نوع میں تبدیل ہوئی ہو، اور اس کی درمیانی صورتیں فوسل ریکارڈ میں محفوظ ہوں؟
ان دونوں نکات میں یہ بات واضح ہے کہ کیلر کے نزدیک ارتقا علمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ نظریہ محض ایک مفروضہ ہے، اس لیے یقینی نہیں۔ مزید یہ کہ یہ نظریہ حقائق سے استنباط کے بجائے، پہلے سے طے شدہ ڈیٹا پر مسلط (masked onto the data) معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا، کیلر ارتقا سے متعلق مابعد الطبیعیاتی (metaphysical) اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک مابعد الطبیعیات کی سطح پر ارتقا اس لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی اساس فطرت پرستی (naturalism) اور اس عمل کو چلانے والی بے ربطی (randomness) پر ہے۔ کیلر کے مطابق دو ایسے دعوے ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتے ہیں (Keller 2011, 359–360):
غیر انسانی انواع (non-human species) میں بڑی ارتقائی تبدیلی (macro-evolutionary transformation) اور تنوع پر ایمان رکھنا بذاتِ خود میرے نزدیک کفر یا شرک نہیں بنتا، الاّ یہ کہ کوئی شخص یہ بھی مانے کہ یہ تبدیلیاں اتفاقی جینیاتی تغیر (random mutation) اور قدرتی انتخاب (natural selection) کے ذریعے واقع ہوئی ہیں،اور ان اوصاف کو اس معنی میں سمجھے کہ یہ سب اللہ کی مشیّت سے بالکل آزاد (causal independence) ہیں۔ آپ کو اپنے دل میں جھانک کر یہ سوال کرنا ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ توحید کے نقطہ نظر سے یہ بالکل واضح ہے کہ کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، کوئی خودمختار فطرت (autonomous nature) نہیں ہے، اور جو بھی شخص ان دونوں باتوں پر ایمان رکھے گا وہ لازماً اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا۔
تیسرا، کیلر کے نزدیک اسلامی متون میں بیان کردہ تخلیق کا تصور انسان کے ارتقائی نظریے سے صریحاً متصادم ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ انسانوں کے ارتقا اور دیگر انواع کے ارتقا کے درمیان فرق ہے۔ اس سلسلے میں وہ دو نکات بیان کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ آدمؑ کی تخلیق جنت میں ہوئی تھی، زمین پر نہیں (Keller 2011, 355):
جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا قرآن میں تخلیق کا بیان انسان کے ارتقا کے ساتھ متعارض ہے، اگر ارتقا، جیسا کہ ڈارون کا خیال تھا، اس بات کو شامل کرتا ہے کہ 'شاید تمام جاندار جو کبھی اس زمین پر رہے ہیں ایک ہی ابتدائی مخلوق سے وجود میں آئے ہیں، جس میں سب سے پہلے زندگی پھونکی گئی تھی' تو میرا فہم یہ ہے کہ یہ قرآن کے بیانِ تخلیق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمارے پہلے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا تھا، زمین پر نہیں۔
کیلر کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تخلیق کا طریقہ کار بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، جو آدمؑ (اور ان کے توسط سے تمام انسانوں) اور باقی حیاتیاتی دنیا کے درمیان نمایاں فرق کو ظاہر کرتا ہے (Keller 2011, 355):
آدمؑ کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا گیا، جسے اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے:
یہ اُس وقت کی بات ہے، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اُسے ٹھیک بنا لوں اور اُس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اُس کے آگے گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے، سب کے سب۔ ابلیس کے سوا، اُس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ (اللہ نے فرمایا:) اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اُس کے آگے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا (واقعی) بڑوں ہی میں سے ہے؟ اُس نے کہا: میں اُس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (القرآن 38 : 71 - 76)
اب رہا خدا تو وہ ہر طرح کے تشبیہی تصورات سے بالاتر ہے۔ فخر الدین رازی اس آیت کے الفاظ، جسے میں نے اپنے [لفظاً: دو] ہاتھوں سے پیدا کیا' کو مجازی تعبیر قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اور التفات ہے جو اس مخصوص مخلوق یعنی پہلے انسان کے لیے ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ ایک عظیم الشان ذات کسی کام کو اپنے "ہاتھوں" سے تب ہی انجام دیتی ہے، جب وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو۔ میں نے "پہلا انسان" اس لیے کہا کہ آیت میں جو عربی لفظ بشر آیا ہے ، اس کا لغوی مفہوم بالکل واضح ہے: یہ صرف "انسان" ہی کے معنی دیتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا لغوی مفہوم نہیں۔
اسی بنا پر کیلر نتیجہ اخذ کرتے ہیں (Keller 2011, 356):
یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کے مطابق انسان اپنی اصل کے اعتبار سے، یعنی جنت میں اپنی پیدائش کی بنا پر، اپنے مخصوص تخلیقی طریقہ کار کی بنا پر، اور اپنی روح کی وجہ سے جو اس کے اندر پھونکی گئی، اللہ کی نگاہ میں دیگر زمینی حیات سے بالکل مختلف مرتبے پر ہے۔ خواہ ان کے جسموں میں بعض جسمانی مشابہتیں دوسری مخلوقات کے ساتھ موجود کیوں نہ ہوں، مگر ان سب کو پیدا کرنا خالق ہی کا اختیار ہے۔
مختصر یہ کہ کیلر کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر انسانی مخلوقات ارتقائی عمل کے ذریعے وجود میں آ سکتی ہیں، اگرچہ وہ سائنسی پہلوؤں پر اپنے تحفظات رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کو وہ اس عمل سے صریحاً خارج کرتے ہیں۔ یوں ارتقا کے بارے میں کیلر کے خیالات کا جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔
اب آتے ہیں یاسر قاضی اور نذیر خان کی طرف۔ یاسر قاضی اور نذیرخان نے ایک امریکی ادارے ، یقین انسٹی ٹیوٹ کے لیے ایک مشترکہ مقالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اسلام اور ارتقا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اگرچہ ان کے افکار میں کئی پہلو کیلر کے نقطہ نظر سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کئی معاملات میں نمایاں فرق بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
مقالے کے بالکل آغاز میں یاسرقاضی اور نذیر خان نے اس موجودہ صورتِ حال کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ اس علمی مکالمے کے شرکا کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے اس موضوع پر روایتی اسلامی علمی روایت کی ہر چیز کو یکسر چھوڑ دیا ہے (Qadhi and Khan 2018, 4):
ایک گروہ نے ارتقائی ماہرین کے نتائج کو من و عن قبول کرنے کے لیے تمام روایتی دینی وابستگیوں کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے۔ انتہاپسندانہ تاویل (radical hermeneutical gymnastics) کے ذریعے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات گویا قدرتی انتخاب (natural selection)، خودبخود حیات کا آغاز (abiogenesis) اور اس جیسے دیگر تصورات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ لیکن اس طرزِ استدلال کا نتیجہ یہ ہے کہ وحی کی صداقت مشتبہ ہو جاتی ہے اور وہ لامحدود طور پر من چاہے معنی میں ڈھل سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ماضی میں ایسی کسی کوشش کو کبھی مثبت نظر سے نہیں دیکھا گیا۔
اس پیراگراف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یاسر قاضی اور نذیر خان کے نزدیک ارتقا کو وحی میں داخل کرنے کی تمام کوششیں اشکال پیدا کرنے والی ہیں۔ ان کی رائے میں یہ طرزِ فکر دراصل قاری کی طرف سے اسلامی متون پر اپنی رائے مسلط کرنا ہے، نہ کہ متن کو اپنے طور پر بولنے دینا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہیں بھی کسی کا نام نہیں لیتے، تاہم غالب گمان ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ ایسے افراد ضرور ہیں جو "بلا استثنا" (no exceptions camp) کے زمرے میں آتے ہیں، جن کا ہم آگے چل کر جائزہ لیں گے۔
یاسر قاضی اور نذیر خان اس کے برعکس ایک دوسرے انتہاپسندانہ موقف کو بھی نمایاں کرتے ہیں، جو حیاتیاتی تنوع (biological diversity) پر سائنس کی تمام آرا کو رد کرنے پر مشتمل ہے (Qadhi and Khan 2018, 5):
دوسری انتہا پر وہ مسلم تخلیقیت پسند (Muslim creationists) ہیں جو ارتقائی سائنس کی ہر چیز کو باطل قرار دیتے ہیں اور جینیات (genetics)، آبادیاتی حرکیات (population dynamics)، اور قدیم حیاتیات (paleontology) میں پیش کیے گئے، ہر ثبوت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موقف محض غیر معقول ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہ مانیں کہ پوری سائنسی برادری ایک بڑی عالمی سازش میں شریک ہے، بلکہ یہ دینی طور پر بھی غیر ضروری ہے، کیونکہ اسلامی متون میں ایسی کسی روش کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ مزید یہ کہ یہ عام مسلمان کو نہایت پیچیدہ سائنسی تحقیقات کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے اور اسے یہ باور کراتا ہے کہ ایک سچا مسلمان بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ان تمام سائنسی ماہرین کو چیلنج کرے جو اپنی تخصیص کے میدان میں برسوں کی محنت سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف بہت سے مسلمان سائنس دانوں کو بھی اس فرضی تناؤ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ گویا ان کے دینی عقائد اور ان کی سائنسی تحقیق ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔
یہاں یاسر قاضی اور نذیر خان اپنی فکرمندی کو واضح کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ سازشی نظریات کے جال میں نہ پھنسے اور ایسا مؤقف اختیار نہ کرے جو پوری سائنسی برادری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہو۔ ان کا اصل محرک یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سائنس اور مذہب کے مابین کسی بھی بظاہر پیدا ہونے والے تصادم سے محفوظ رکھا جائے۔ تاہم، ان کی تحریر سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے سائنس کے مذہبی یا الٰہیاتی معاملات سے متعلق تمام دعوؤں کو بلا تنقید قبول نہیں کیا جا سکتا۔
مختلف انتہاؤں کو واضح کرنے کے بعد یاسر قاضی اور نذیر خان یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ ایک متوازن نقطہ نظر کی سخت ضرورت ہے، اور غالباً یہی خلا ان کا مذکورہ مضمون پُر کرنا چاہتا ہے (Qadhi and Khan 2018, 5):
جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو اب تک مفقود رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وحی اور سائنس کے تعلق پر ایک سنجیدہ اور تنقیدی جائزہ لیا جائے اور اکیڈمک سطح پر مکالمہ کیا جائے۔ اس متوازن طرزِ فکر کا تقاضا یہ ہوگا کہ جہاں سائنسی تحقیق کی علمی ساکھ کو تسلیم کیا جائے، وہیں عوامی سطح پر پھیلائی جانے والی نام نہاد سائنس (pseudoscience) اور اس کی مبالغہ آمیز تعبیرات پر تنقید بھی کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامی متون پر مزید گہرے غور و فکر کے ذریعے یہ طے کیا جائے کہ انسان کی ابتدا اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اس کے مقام و مرتبے سے متعلق کون سے الٰہیاتی نتائج اعتماد کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔
منظرنامے کا خلاصہ کرنے کے بعد یاسر قاضی اور نذیر خان تین مختلف تاویلی طریقوں پر بات کرتے ہیں جو کلاسیکی اسلامی روایت میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی ابنِ سینا، امام غزالی اور ابنِ تیمیہ کے طریقے۔
ابتدا وہ ابنِ سینا سے کرتے ہیں، جو اسلامی فکری تاریخ میں فلسفیانہ روایت نیو افلاطونی-ارسطوی (Neoplatonic-Aristotelian) کے نمائندہ ہیں۔ یاسر قاضی اور نذیر خان کے نزدیک ابنِ سینا کا زاویہ نظر تاویل کے باب میں ایک "پنڈورا بکس" کی مثال رکھتا ہے۔ ابنِ سینا کے مطابق انبیا کی زبان دراصل فلسفیانہ حقائق کا بیان ہے جو زیادہ تر علامتی اور تمثیلی اسلوب میں عوام کی فہم کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ ، جنہیں مسلمان حقیقی مانتے ہیں، ابنِ سینا کے نزدیک ایسی حقیقتوں کی علامت ہیں جو انسانی تخیل سے ماورا ہیں۔ مزید یہ کہ اگر کبھی فلسفیانہ حقائق (جن میں سائنسی معلومات بھی شامل ہیں) اسلامی متون سے متصادم دکھائی دیں تو ان متون کو لازماً مجازی انداز میں سمجھا جانا چاہیے (Qadhi and Khan 2018, 8–9)۔ اسی بنا پر یاسر قاضی اور نذیر خان (2018, 9) لکھتے ہیں: "اس نقطہ نظر میں تاویل کی کوئی حد باقی نہیں رہتی، اس طریقے کو آگے بڑھا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز، روزہ، بلکہ خدا کا تصور بھی محض علامتیں ہیں۔"
اس کے بعد یاسر قاضی اور نذیر خان امام غزالی کی طرف آتے ہیں، جو علمِ کلام کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں۔ امام غزالی ابنِ سینا کے متعدد پہلوؤں پر ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک خاص اعتراض ابنِ سینا کی قرآن میں مذکور معجزات کی مجازی تاویلات پر بھی ہے۔ امام غزالی بظاہر متون اور عقل کے درمیان پائے جانے والے تصادم میں عقل کے استعمال کے مکمل حامی ہیں، کیونکہ انہی کے نزدیک قرآن کی صداقت کا تعین عقل ہی کے ذریعے ممکن ہے (اس پر تفصیل باب 9 میں آئے گی)۔ تاہم جہاں تک قرآن کی تعبیر کا تعلق ہے، ان کا اصول یہ ہے کہ اسلامی متن کو ظاہری مفہوم (literal face value) پر ہی لیا جائے، الا یہ کہ کوئی مضبوط اور منطقی برہانی استدلال موجود ہو جو مجازی تاویل کو ناگزیر بنا دے (Qadhi andKhan 2018, 9)۔ اس پر بھی باب 9 میں مزید تفصیل آئے گی۔
مثال کے طور پر، قرآن میں اللہ کے "ہاتھ" کا ذکر۔ امام غزالی کے نزدیک یہ الفاظ حقیقی معنوں میں ہاتھ کی طرف اشارہ نہیں کرتے، کیونکہ خدا نہ تو زمان و مکان کا پابند ہے اور نہ ہی مادی جسم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ خدا کے پاس حقیقی ہاتھ ہیں، غیر منطقی ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں جنہیں ابنِ سینا علامتی مانتے تھے جیسے جنت اور دوزخ، امام غزالی کے نزدیک اپنے ظاہری معنی پر ہی لی جائیں گی، کیونکہ انہیں رد کرنے کی کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں۔ یاسر قاضی اور نذیر خان امام غزالی پر کسی نکتہ نظر سے تنقید کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس طرزِ فکر کو قابلِ قبول سمجھتے ہیں۔
آخر میں یاسر قاضی اور نذیر خان امام ابنِ تیمیہ کی طرف آتے ہیں۔ ان کے فکری سانچے میں نہ تو تخییل کی ضرورت ہے اور نہ ہی تاویل کی۔ تصادم کی صورت میں ابنِ تیمیہ وحی کو ترجیح دیتے ہیں۔ غزالی کی طرح وہ بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عقل وحی کے اثبات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وحی کے بیان کو بغیر کسی شرط کے تسلیم کرے اور اسے انسانی عقل کی ناقص اور محدود آرا کی بنیاد پر چیلنج نہ کرے (Qadhi and Khan 2018, 10)۔
ابنِ تیمیہ کے نزدیک وحی کی تائید فلسفیانہ دلائل کے بجائے فطرت سے بھی ہوتی ہے، اور یہی ان کے فکری نظام کا ایک نمایاں اور مخصوص پہلو ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ کے ہاں وحی عقل سے زیادہ وزنی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یاسر قاضی اور نذیر خان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے ہاں عقل اور وحی کی دوئی موجود ہی نہیں، کیونکہ عقل دین کا جزوِ لاینفک ہے۔ یہی ابنِ تیمیہ اور ابنِ سینا و غزالی کے درمیان ایک بڑا امتیازی فرق ہے۔ چنانچہ ان کے بقول اہم یہ ہے کہ دلیل قطعی ہو، خواہ وہ نقلی ہو یا عقلی۔ جب کوئی نقلی شہادت واضح اور غیر مبہم ہو تو وہاں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں (Qadhi and Khan 2018, 10)۔ البتہ جہاں کسی نص میں ابہام ہو اور اس کے متعدد ممکنہ معانی نکلتے ہوں، وہاں کسی بھی ایسے مفہوم کو اختیار کیا جا سکتا ہے جو زبان، عقل اور سائنس کے دائرے میں آتا ہو۔
تاہم یاسر قاضی اور نذیر خان (2018, 10) یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مجازی تاویل نہیں ہے، بلکہ کسی لفظ کے متعدد لغوی معانی میں سے ایک ایسے معنی کو اختیار کرنا ہے جو قطعی دلائل کی روشنی میں زیادہ موزوں ہو۔ اس کی مثال کے طور پر وہ قرآن میں "ستۃ ایام (چھ دن)" کے ذکر کو پیش کرتے ہیں، جسے عام طور پر چھ دنوں کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن لفظ ایام اپنے مفہوم میں وسیع ہے اور یہ کسی بھی مدتِ زمانہ پر دلالت کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسے چھ چوبیس گھنٹوں کے دن بھی سمجھا جا سکتا ہے اور چھ مختلف ادوارِ وقت بھی (Qadhi and Khan 2018, 11)۔
یاسر قاضی اور نذیر خان کے نزدیک ان مختلف نقطہ ہائے نظر کے مضمرات نہایت اہم ہیں (Qadhi and Khan 2018, 11):
انسان کی ابتدا کے قصے کے معاملے میں ہمارے پاس ایک بالکل واضح بیان موجود ہے، جو قرآن کے بے شمار مقامات اور ان گنت نبوی بیانات (احادیث) میں نہایت گہرائی کے ساتھ رچا بسا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے ہی وہ بات مانیں جس پر اللہ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہے۔ الفاظ، صفات اور افعال کی جو کثرت اور تنوع یہاں استعمال ہوا ہے، وہ کسی بھی قسم کی لسانی تاویل کو ناقابلِ قبول بنا دیتا ہے۔ اسی دوران، اس پورے بیان کو علامتی یا تمثیلی قرار دینے کی کوشش بعض معاصر مسلم سائنس دانوں کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ طرزِ فکر منطقی طور پر غیر مربوط الٰہیاتی نتائج پیدا کرتا ہے اور قرآن کے اپنے اس اصرار کی نفی کرتا ہے کہ یہ بیانات بالکل حقیقی واقعات ہیں (3:62)۔ اس کے برعکس، ایک ایسی علمی و معرفتی مضبوط بنیاد قائم کرنا جس پر وحی اور سائنس دونوں کی صداقتیں ہم آہنگی کے ساتھ کارفرما ہوں، کہیں زیادہ نتیجہ خیز کوشش ہے۔
اس عبارت میں یاسر قاضی اور نذیر خان کھل کر بیان کرتے ہیں کہ نہ تاویل اور نہ ہی تخییل قرآن کی ایسی تعبیر میں مدد دے سکتے ہیں جس کے ذریعے ارتقا کو متن میں داخل کیا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں طریقے داخلی طور پر غیر مربوط ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ یاسر قاضی اور نذیر خان دراصل ابنِ سینا اور غزالی کو براہِ راست تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ ان کے ایسے تاویلی طریقوں پر تنقید کر رہے ہیں جنہیں ارتقائی تعبیرات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یاسر قاضی اور نذیر خان کے نزدیک تخلیق کا بیانیہ، جیسا کہ باب 3 میں بیان ہوا ہے، ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ مجموعی طور پر قرآنی شہادتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ آدمؑ کے لیے کسی بھی قسم کے "والدین" کے تصور کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارتقا کو مکمل طور پر رد کر دیا جائے۔ اگرچہ آدمؑ اور ان کی اولاد کے ارتقا کو تسلیم کرنا خارج از امکان ہے، لیکن وہ نہایت وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلمان ارتقا کے دیگر کئی پہلوؤں کو قبول کر سکتے ہیں: اسلامی متون میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو ابایوجینیسس (abiogenesis)، جینیاتی تغیر و تنوع (genetic mutation and diversification)، قدرتی انتخاب (natural selection)، ہومینڈ انواع (hominid species) کے وجود، یا زمین پر تمام حیاتیاتی زندگی کے ایک مشترکہ جدِ امجد (common ancestor) کے تصور کی صریح نفی کرتی ہو۔ استثنا صرف یہ ہے کہ آدم اور ان کی نسل اس عمومی قاعدے سے الگ ہیں (Qadhi and Khan 2018, 12)۔
چونکہ قرآن آدم کی تخلیق کو ایک معجزہ کے طور پر بیان کرتا ہے، اس لیے قاضی اور خان بھی کیلر کی طرح human exceptionalism (انسانی امتیاز) کے قائل دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم، کیلر کے برعکس وہ اسلام اور انسانی ارتقا کے درمیان کسی ممکنہ ہم آہنگی کے امکان کو سرے سے رد نہیں کرتے، اور یہی پہلو ان کے مؤقف کو منفرد بناتا ہے۔
یاسرقاضی اورنذیر خان کی فکر کی کلید سائنسی حقیقت پسندی (scientific realism) پر فلسفیانہ غور و فکر ہے۔ یہ فلسفہ سائنس میں ایک نہایت اہم بحث ہے جو اس سوال کے گرد گھومتا ہے کہ سائنسی مساوات اور نظریات ہمیں کیا بتاتے ہیں اور ہم ان پر کس حد تک یقین کر سکتے ہیں۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے جو وہ براہِ راست مشاہدہ (direct observation) اور غیر مستقیم مشاہدہ (indirect observation) کے درمیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی بھی دعویٰ جو براہِ راست مشاہدے پر قائم ہو، وہ تجرباتی طور پر درست ہے اور اسی بنا پر اسے "حقیقت" مانا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس غیر مستقیم مشاہدے ایسے ہیں جو مختلف تفسیروں، استدلالوں، نمونوں، قیاس آرائیوں، اور مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ تجرباتی طور پر مناسب دکھائی دیں (Qadhi and Khan 2018, 15)۔ اس لیے ایسے دعووں کا علمی وزن کم ہوتا ہے، اور چاہے کوئی سائنسی حقیقت پسندی کے کسی بھی درجے کا قائل ہو، وہ براہِ راست مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ "جہاں تک غیر مشاہدہ شدہ حقائق کا تعلق ہے، وہاں سچائی کے طور پر ہم جو کچھ مان سکتے ہیں، وہ نہایت محدود ہے" (Qadhi and Khan 2018, 15)۔
یہی وہ مقام ہے جہاں سے سائنسی حقیقت پسندی پر بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے مکالمے کے لیے نہایت اہم ہے: سوال یہ ہے کہ کسی شے کے وجود کو کس حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے، یا ہم کس بنیاد پر کسی غیر مشاہدہ شدہ چیز کے وجود پر ایمان قائم کر سکتے ہیں جسے سائنس پیش کرتی ہے؟ اس مسئلے پر آرا کا ایک وسیع سلسلہ پایا جاتا ہے، جسے ایک سپیکٹرم (spectrum) کی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے۔
اس فکری سپیکٹرم کے ایک سرے پر سائنسی حقیقت پسندی ہے، جو یہ موقف رکھتی ہے کہ سائنسی نظریات اور مساوات جو کچھ پیش کرتے ہیں، ان پر مضبوط یقین کیا جائے، خواہ وہ ابھی تک تجرباتی طور پر ثابت نہ ہوئے ہوں۔ اس کے برعکس، سپیکٹرم کے دوسرے سرے پر مختلف اقسام کی سائنسی غیر حقیقت پسندی موجود ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں مثال انسٹرومنٹل ازم (instrumentalism) کا نظریہ ہے، جس کے مطابق سائنس محض ایسے اوزار فراہم کرتی ہے جو کارآمد تو ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت کی درست نمائندگی بھی کرتے ہوں۔ جب تک "یہ کام کر رہا ہے"، یہی کافی ہے۔ البتہ اس سے کائنات کی کسی جامع اور حتمی تفہیم تک نہیں پہنچا جا سکتا (Chakravartty 2017)۔
اسی تناظر میں کثرتِ کائنات (multiverses) پر ہونے والی بحث کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو بعض اوقات سٹرنگ تھیوری کی پیداوار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں صرف اس بنا پر کثرتِ کائنات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ایک نظریاتی امکان ہے، حالانکہ اس کے ثبوت موجود نہیں؟ یا پھر اسے محض ریاضیاتی فرضی ڈھانچے (mathematical artefacts) کے طور پر سمجھا جائے؟ (Wolt 2007; Kragh 2011)۔ ان مختلف پوزیشنوں کے درمیان جوں جوں حرکت کی جاتی ہے، بحث مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے (Chakravartty 2017; Ladyman 2020)۔ کیا سائنس ہمیں چیزوں (entity realism) کا انکشاف کرتی ہے یا صرف ڈھانچوں (structural realism) کا؟ اور کیا یہ وابستگیاں محض علمی (epistemic) ہیں یا وجودی (ontological) بھی؟ ان سب مختلف آرا کو سامنے رکھتے ہوئے یاسر قاضی اور نذیر خان نہایت وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سائنسی حقیقت پسندی کی کسی سخت اور جازم صورت کے حامی نہیں ہیں (2018, 15):
جب براہِ راست مشاہدہ کی جانے والی چیزوں کی بات ہو تو تجرباتی درستی (empirical adequacy) ہی سچائی کے مترادف ہے۔ لیکن جب غیر مشاہدہ شدہ امور کی بات آتی ہے تو ہم محض تفسیروں، استدلالوں، نمونوں، قیاس آرائیوں اور مفروضوں پر انحصار کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تجرباتی طور پر درست دکھائی دیں۔ سائنسی حقیقت پسندی کی غیر ضروری مابعد الطبیعیاتی زیادتیوں سے بچنے کی کوشش میں اس کی مختلف ذیلی صورتیں سامنے آئیں، جیسے امپریکل اسٹرکچرل ریئلزم (empirical structural realism)، آنٹک اسٹرکچرل ریئلزم (ontic structural realism)، سیمی ریئلزم (semi-realism) وغیرہ۔ تاہم تقریباً تمام گروہوں کا ایک مشترک نکتہ یہ ہے کہ جب غیر مشاہدہ شدہ امور کی بات آتی ہے تو حقیقت کے طور پر ہم جو کچھ مان سکتے ہیں وہ نہایت محدود ہے۔
اس وضاحت کے بعد یاسر قاضی اور نذیر خان غیب (unseen) سے متعلق الٰہیاتی بحث کی طرف بڑھتے ہیں، مثلاً جنت، دوزخ اور خدا سے متعلق۔ انسانی وجود کی ابتدا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ "کوئی انسان ماضی میں واپس جا کر یہ طے نہیں کر سکتا کہ آدم اور حوا کے وقت بالکل کیا ہوا تھا، لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تجرباتی طور پر ناقابلِ مشاہدہ ہے، اور اسی لیے یہ غیب کے زمرے میں آتا ہے" (Qadhi and Khan 2018, 15)۔
اس بیان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں غیب سے کیا مراد ہے۔ ابنِ تیمیہ کی بحث کے مطابق غیب کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں، اگرچہ یاسر قاضی اور نذیر خان نے ان اقسام کا ذکر نہیں کیا۔ پہلی قسم ہے غیبِ مطلق، یعنی وہ چیزیں جو سب سے پوشیدہ ہیں، جیسے جنت اور دوزخ۔ دوسری قسم ہے غیبِ مقید، یعنی وہ حقائق جنہیں بعض لوگوں نے براہِ راست دیکھا لیکن دوسروں تک وہ صرف وحی کے ذریعے پہنچے دیکھیے: (Jalajel 2018)۔ اس میں ماضی بعید کے وہ واقعات شامل ہیں جن کے کوئی مادی شواہد موجود نہیں، مثلاً انبیائے سابقین کے قصے۔ ہمارے لیے موجودہ دور میں آدمؑ کی تخلیق بالکل غیب کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ ہم انسانی ذرائع سے کسی مخصوص فرد "آدم" اور اس کی معجزانہ تخلیق کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ البتہ یہ اس کے اہل خانہ، بیوی اور اولاد کے لیے غیب نہیں تھا، جنہوں نے انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس اعتبار سے آدمؑ غیبِ مقید کے ذیل میں آتے ہیں۔
یاسر قاضی اور نذیر خان سائنس میں حقیقت پسندی اور غیب کے اس تصور کو جوڑ کر یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ آدمؑ کا معاملہ سائنسی لحاظ سے غیر متعلق (empirically irrelevant) لیکن دینی لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ چونکہ آدمؑ غیبِ مقید کے زمرے میں ہیں، لہٰذا تعریف کے لحاظ سے سائنس انہیں جان ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سائنس نہ آدمؑ کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے اور نہ رد کر سکتی ہے: (Qadhi and Khan 2018, 1518)
جب ہم ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے کے کسی غیر مشاہدہ شدہ زمانے کے بارے میں نظریات تشکیل دیتے ہیں، تو ہم صرف ان شواہد کی تفسیروں کی بنیاد پر نتائج اخذ کر سکتے ہیں جو آج تک محفوظ ہیں۔ ہم ایسا کوئی تجربہ ترتیب نہیں دے سکتے جو ہزاروں سال پیچھے جا کر یہ براہِ راست متعین کرے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔
یہ نکتہ ڈیوڈ سولومون جَلالجل (David Solomon Jalajel) بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا ہم آگے جا کر جائزہ لیں گے۔ اگر صورتحال یہی ہے تو پھر ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ اس مقام پر یاسر قاضی کا مشہور ڈومینو استعارہ (domino analogy) سامنے آتا ہے، جس کا ذکر وہ اپنے کئی وڈیو لیکچرز میں کر چکے ہیں (Moran 2020)۔ اس مثال کا تصور کچھ یوں ہے کہ ایک قطار میں رکھے ڈومینوز ہیں۔ اگر آپ پہلے ڈومینو کو گرا دیں تو باقی تمام ڈومینوز ترتیب وار گر جاتے ہیں۔ لیکن اب فرض کریں کہ ایک قطار پہلے سے گری ہوئی ہے اور کوئی شخص آخر میں ایک اور گرا ہوا ڈومینو لا کر شامل کر دیتا ہے۔ کوئی تیسرا شخص جو اس پوری گری ہوئی قطار کو دیکھے گا، یہ اندازہ نہیں کر سکے گا کہ آخری ڈومینو اس سلسلہ وار گرنے کا حصہ نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح یاسر قاضی اور نذیر خان استدلال کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ارتقائی عمل جاری تھا، اور اسی دوران جب انسانوں کے ظاہر ہونے، نمودار ہونے یا ارتقا پذیر ہونے کا مرحلہ آیا، تو آدمؑ معجزانہ طور پر نمودار ہوئے، جیسا کہ جدول 4.1 میں دکھایا گیا ہے، یہ جدول اصل کتاب کے صفحہ 131 پر موجود ہے۔ یہ تعبیر الٰہیاتی اعتبار سے بالکل ممکن ہے اور سائنسی نقطہ نظر سے ناقابلِ ابطال ہے (Qadhi and Khan 2018, 12):
یقیناً ایک ایسا منظرنامہ سوچا جا سکتا ہے جس میں ہومینڈ انواع (hominid species) زمین پر بتدریج ارتقا پذیر ہو رہی ہوں، اور بالکل اسی مرحلے پر جب ارتقائی ماہرین جدید انسان کے نمودار ہونے کی پیش گوئی کریں، اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر آدم کی اولاد کو وجود بخش دے۔ فرض کیجیے کہ یہ "آدمی نوع" (Adamic species) حیاتیاتی، جسمانی، فزیولوجیکل اور جینیاتی طور پر بالکل انہی انواع سے غیر ممیز ہوں جس کی ارتقائی تاریخ میں پہلے سے موجود آبادی کے تسلسل کی بنیاد پر سامنے آنے کی توقع تھی۔ وہ ارتقائی شجرہ نسب میں بالکل اسی مقام پر دکھائی دیں۔ ایسے منظرنامے کا واقع ہونا الٰہیاتی طور پر بالکل ممکن ہے، اور چونکہ یہ ایک ما بعد الطبیعیاتی دعویٰ ہے، اس لیے تجرباتی طور پر اس کی تردید ناممکن ہے۔
اس بیان کے مطابق آدمؑ کو بالکل صحیح حیاتیاتی ساخت کے ساتھ بالکل صحیح وقت پر پیدا کیا گیا، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ارتقائی عمل کا ایک مربوط حصہ ہوں۔
تاہم یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ کسی قسم کی خدائی فریب دہی (divine deception) تو نہیں؟ یاسر قاضی اور نذیر خان اس سوال کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور اس کے دو جوابات پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر یہ اصل اختلاف کا نقطہ ہے تو پھر یہ سائنس کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک الٰہیاتی سوال بن جاتا ہے جو سائنس دانوں کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ البتہ ان کا یہ جواب براہِ راست سائنس دانوں کے لیے نہیں بلکہ اُن لوگوں کے لیے ہے جنہیں وہ مذہب دشمن کہتے ہیں (Qadhi and Khan 2018, 13):
کوئی مذہب مخالف یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس طرح کیوں پیدا کیا کہ وہ دیگر حیاتیاتی انواع سے مشابہ نظر آئیں اور ارتقا کے مطابق دکھائی دیں۔ لیکن یہ اعتراض دراصل ایک کمزور الٰہیاتی اعتراض ہے (کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا) نہ کہ کوئی سائنسی اعتراض۔
مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں مراد دراصل بعض ایسے ملحدین ہیں جو مذہب کے خلاف موقف رکھتے ہیں اور ارتقا کو مذہب کے لیے ایک فیصلہ کن رد کے طور پر پیش کرتے ہیں، مثلاً رچرڈ ڈاکنز (Richard Dawkins) اور ڈینیئل ڈینیٹ (Daniel Dennett)۔ جب وہ خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر وہ الٰہیات میں دخل اندازی کر کے یہ طے کیوں کر رہے ہیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں؟
یاسر قاضی اور نذیر خان کا دوسرا جواب اس اعتراض کو براہِ راست مخاطب کرتا ہے۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ خدا وحی کے ذریعے انسانوں کو انسانی تاریخ کے معجزانہ آغاز سے باخبر کرے، اگرچہ یہ بات سائنس کے ذریعے دریافت نہ ہو سکے۔ دونوں کو وہ علم کے درست ذرائع سمجھتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی سابقہ بحث میں سائنسی حقیقت پسندی اور غیب کے بارے میں آیا، انسانی صلاحیتیں لازمی طور پر ان امور تک نہیں پہنچ سکتیں جو غیب کا حصہ ہیں، الا یہ کہ وحی کے ذریعے ان کا علم دیا جائے۔ اس لیے وحی میں ایسے قطعی بیانات شامل ہیں جو خدا نے انسانوں کو عطا کیے اور جو وہ محض اپنی عقل یا تجربے سے نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ "الٰہیاتی نقطہ نظر سے اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں کہ خدا ہمیں وحی کے ذریعے ہماری آسمانی اصل کی خبر دے، جبکہ ہماری حیاتیاتی ساخت ہمیں زمینی سفر کی یاد دہانی کراتی رہے" (Qadhi and Khan 2018, 13)۔
وہ قرآن میں بیان کردہ ایسے معجزات کی مثال دیتے ہیں جنہیں جدید سائنس اپنی موجودہ حدود میں شاید کبھی تسلیم نہ کرے، مثلاً حضرت موسیٰؑ کا عصا سانپ میں بدل جانا، حضرت ابراہیمؑ کا آگ میں ڈالے جانے کے باوجود سلامت رہنا، یا نبی اکرم ﷺ کا چاند کو شق کرنا۔ اسی طرح فرشتے، جنات، جنت اور دوزخ ، جو زمان و مکان کی دنیا کا حصہ نہیں سمجھی جاتیں، اس لیے سائنس کے دائرۂ کار سے باہر ہیں، لیکن اسلامی عقیدے کا بنیادی جزو ہیں۔ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ سب چیزیں یا تو ناقابلِ فہم ہیں یا پھر ناممکن سمجھی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک یہ بالکل حقیقی اور برحق ہیں۔
چنانچہ وحی اُن 'اندھی جگہوں' (blind spots) کو پُر کرتی ہے جہاں سائنس خاموش یا بے بس ہے (Yazicioglu 2013)۔ یہی نکتہ یاسر قاضی اور نذیر خان کی سائنسی حقیقت پسندی سے متعلق بحث کو مزید تقویت دیتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ یاسر قاضی اور نذیر خان کا موقف قرآن میں بیان کردہ آدمؑ کے بیانیے کو محفوظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی فطری علوم کو ان کی جائز علمی حدود سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس طرح، اگرچہ وہ بھی کیلر کی طرح human exceptionalism کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ اس کے نتیجے میں ارتقا کو مکمل طور پر رد کرنا لازمی ہے۔ یہ اس تیسرے اصول کی نمایاں مثال ہے جو پہلے ذکر کی گئی درجہ بندی میں شامل ہے۔ یعنی کوئی مفکر ارتقا کو کلی طور پر یا جزوی طور پر مسترد کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایسی تطبیقی صورتیں تجویز کر سکتا ہے جو مذہب اور سائنس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں۔
(جاری)