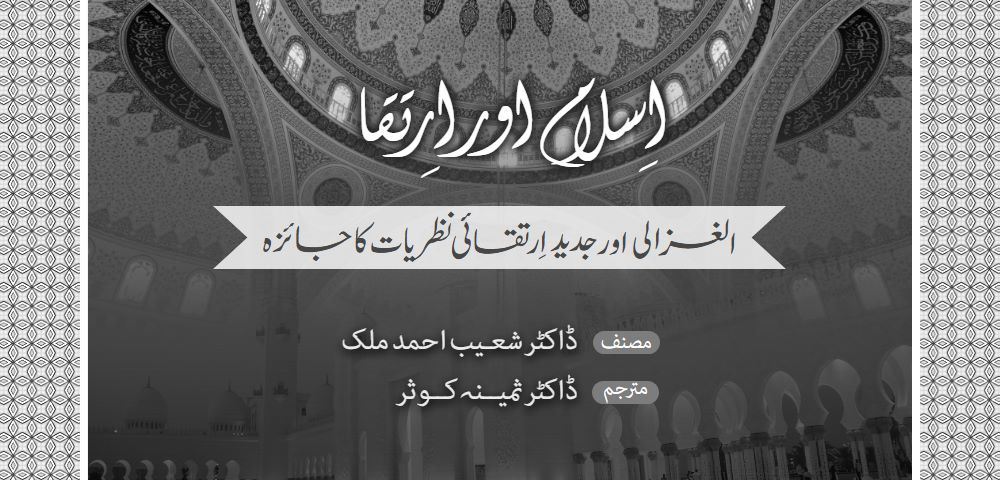مسلم زاویہ فکر
اسلام اور نظریہ ارتقا کے علمی و تحقیقی مباحث میں جیسے جیسے وسعت اور ترقی آ رہی ہے، متعدد آرا سامنے آ رہی ہیں۔ اس موضوع پر دنیا کے مختلف خطوں جیسے کہ امریکہ، ہندوستان، پاکستان، ترکی، مشرقِ وسطیٰ، ملیشیا اور ایران کے اہل علم کی آرا پر مشتمل تحریری سرمایہ دستیاب ہے (Ziadat 1986; Nadvi 1998; Hanioğlu 2005; Riexinger 2009; Howard 2011; Kaya 2011; Elshakry 2013; Bigliardi 2014; Ibrahim, and Baharuddin 2014; Bilgil 2015; Determann 2015; Varisco 2018; Ibrahim et al. 2019; Qidwai 2019; Daneshgar 2020)۔ چونکہ دائرہ بحث محدود ہے، اس سارے لٹریچر کا احاطہ ممکن نہیں۔ اس باب (اور باب دہم جہاں ان آرا کو امام غزالی کے ہرمنیوٹک فریم ورک کے تحت پرکھا جائے گا) میں کن اہلِ فکر کی آراء کو شامل کیا جائے، اس کے لیے تین اصول متعین کیے گئے۔
اوّل، معاصر اہلِ فکر کو ترجیح دی گئی۔ دوم، صرف ان اہل علم کا انتخاب کیا گیا جن کے نام سے اس موضوع پر خاطر خواہ علمی سرمایہ موجود ہے (سوائے ذاکر نائیک کے جنہیں ایک خاص وجہ سے استثنا دیا گیا)۔ بعض اہلِ علم نے ارتقا پر اپنی رائے محض ایک پیراگراف یا حاشیے میں بیان کی ہے، جس سے یہ متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس پہلو سے اتفاق یا اختلاف کر رہے ہیں (کیا عمومی ارتقا سے؟ انسانی ارتقا سے؟ طویل زمانی تسلسل سے؟ یا مکینزم سے؟)۔ سوم، ان اہلِ فکر کو ترجیح دی گئی جن کے اندازِ استدلال یا طرزِ فکر میں نسبتاً انفرادیت پائی جاتی ہے، خواہ وہ ارتقا کو کسی درجے میں قبول کریں یا رد کریں۔ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک ہی موضوع پر اہلِ علم مختلف طرزِ استدلال سے کسی موقف تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آگے دیکھیں گے، بعض اوقات اہلِ فکر ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں لیکن ان کی بنیادیں اور طریقہ استدلال مختلف ہوتا ہے، اور وہ تطبیق یا عدمِ تطبیق کے الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔
ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل بیس اہل فکر کا انتخاب کیا گیا ہے جیسا کہ اصل کتاب کے صفحہ 113 پر موجود جدول 4.3 میں درج ہے۔ ان میں تخلیقیت (Creationism) اور "کسی استثنا کے بغیر" (No Exceptions) کے زاویے میں آٹھ آٹھ اہلِ فکر شامل ہیں۔ انسانی استثنا (Human Exceptionalism) میں تین اہلِ فکر اور آدمی استثنا (Adamic Exceptionalism) میں ایک اہلِ فکر شامل ہیں۔ اس وضاحت کے بعد اب ان تمام زاویہ ہائے فکر کے نمائندہ اہلِ علم کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
تخلیقیت (Creationism)
اس مکتبِ فکر کے حامی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام جانداروں کی کوئی مشترکہ اصل (Common Ancestry) سرے سے موجود ہی نہیں۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اس نتیجے تک پہنچے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر باب اوّل میں آ چکا ہے۔ بعض اہلِ فکر ارتقا کے رد میں کئی دلائل فراہم کرتے ہیں، جب کہ کچھ صرف ایک یا دو بنیادی باتیں پیش کرتے ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے یہاں جب ہم مختلف اہلِ فکر کی آرا کا جائزہ پیش کریں گے تو ایک مفکر کے اعتراضات کو دوسرے کے ضمن میں دہرانے سے گریز کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کسی مشترک رجحان کو نمایاں کرنا مقصود ہو۔
ابتداءً بعض افراد ارتقا کو محض اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ اسے "بس ایک نظریہ" سمجھتے ہیں۔عالمی شہرت یافتہ مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائیک کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں۔ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ لفظ "نظریہ" کا عام مفہوم اور سائنسی مفہوم ایک ہی ہے (Samuel and Rozario 2010; Gardner et al. 2018, 383) ۔ بظاہر اس کی بنیاد یہ سوچ ہے کہ ارتقا اسلامی نصوص سے ہم آہنگ نہیں۔ اس لیے اگرچہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ارتقا ایک غیرمضبوط یا خام مفروضہ ہے، لیکن اس کے پسِ پردہ مذہبی اسباب بھی کارفرما ہو سکتے ہیں۔ دیگر تخلیقیت پسند یا توذاکر نائیک کے طرزِ استدلال کو دہراتے ہیں یا پھر ارتقا کو ایک ناقابلِ اعتبار سائنسی نظریہ قرار دے کر رد کر دیتے ہیں۔ ان کے اعتراضات زیادہ تر امریکی تخلیقیت پسندوں کے اعتراضات سے مشابہ ہیں، جن پر باب دوم میں بحث ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ اہلِ فکر ارتقا کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ سائنسی طور پر ناقابلِ قبول ہے۔ ایرانی و امریکی مفکر سید حسین نصر اور ان کے شاگرد، ملائشین مذہبی اسکالر عثمان بکر ارتقا کے سائنسی پہلوؤں پر تنقید کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں موجود اتفاقی میکانزم، نظریے میں پائے جانے والے خلا، بار بار ہونے والی تاریخی ترامیم جن سے یہ نظریہ مسلسل بحران کا شکار دکھائی دیتا ہے، اور حیات کے آغاز سے متعلق سائنسی مشکلات وغیرہ۔ تاہم ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ارتقا کو ما بعد الطبیعیاتی بنیادوں پر بھی رد کرتے ہیں۔ دونوں ایک Neoplatonic تصورِ کائنات کے حامی ہیں جس کے مطابق ماہیات جامد اور غیر متبدل ہیں۔ اس بنا پر ارتقا ممکن ہی نہیں۔ حسین نصر اس کی وضاحت ایک مثلث کی مثال دے کر کرتے ہیں: "مثلث مثلث ہی ہے اور کوئی چیز تدریجی طور پر مثلث میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایک مثلث مکمل طور پر مثلث نہ ہو جائے، وہ مثلث نہیں ہے۔ اسی طرح جانداروں کی بھی اپنی اپنی حتمی صورت ہے" Nasr (2006, 183) ۔ عثمان بکر اس پیرا ڈائم کو مزید کھولتے ہیں:
ایک نوع (Species) دراصل خدا کے ذہن میں موجود ایک ’’خیال‘‘ ہے جو اپنی تمام ممکنات کے ساتھ ازل سے موجود ہے۔ یہ کوئی انفرادی حقیقت نہیں بلکہ ایک مثالی صورت (archetype) ہے، اور اسی لیے یہ نہ تو کسی حد کا پابند ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ مثالی صورت سب سے پہلے لطیف درجے میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں ہر فرد ایک ’’صورت‘‘ (form) اور ایک لطیف مادے کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ یہ ’’صورت‘‘ اس نوع کی بنیادی خصوصیات کا مجموعہ ہے جو اس کی غیر متبدل ماہیت کی جھلک ہوتی ہے۔Bakar (1984)
چنانچہ حسین نصر اورعثمان بکر کے نزدیک ہر شے کی ایک مقررہ اور غیر متبدل مثالی صورت (archetype) ہے۔ اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ارتقا ممکن نہیں۔ البتہ واضح رہے کہ ان کا نقطہ نظر صغروی ارتقا (microevolution) کو تو رد نہیں کرتا، لیکن کبروی ارتقا (macroevolution) کو ناممکن قرار دیتا ہے۔وہ لکھتے ہیں:
مائیکرو ایوولیوشن (micro-evolution) کا امکان ضرور ہے، لیکن میکرو ایوولیوشن (macro-evolution) کا نہیں۔ مائیکرو ایوولیوشن دراصل کسی نوع کی مثالی صورت archetype یا form کے اندر ہی رہتے ہوئے تبدیلی ہے۔ جیسے کہ آپ اور میں انسان ہیں، اور چینی یا جاپانی لوگ بھی انسان ہیں۔ ہماری آنکھوں کی ساخت کچھ مختلف ہے، ان کی کچھ اور۔ اگر ہم زمبابوے جائیں تو ہماری جلد کا رنگ زیادہ سیاہ ہو جائے گا، اور اگر ہم سویڈن جائیں تو کچھ زیادہ سفید ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ انسان کی بنیادی صورت کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے۔ اس طرح کی چھوٹی تبدیلیاں مائیکرو ایوولیوشن ہیں۔ اسی طرح مکھیوں کا کچھ بڑی ہو جانا، یا روشنی کے مختلف اثرات کے تحت پودوں کا ردعمل ظاہر کرنا، ان کو بعض لوگ انواع کی تبدیلی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ نوع کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ہی نوع کے اندر ہونے والی ارتقائی تبدیلی ہے۔ہر نوع کی ایک وسعت اور دائرہ ہے جو اس نوع کے انفرادی وجود سے بڑا ہے۔ اسی لیے اس نوع میں مختلف افراد نئی خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہو سکتے ہیں یا ماحولیاتی حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو گئی۔ (Nasr 2006, 184–185)
ان اعتراضات کے علاوہ، ان کے نزدیک ارتقا کے نظریے میں فلسفیانہ مسائل بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے بنیادی نکات naturalism اور reductionism کے مسائل ہیں۔ ارتقا ایک مادیت پرستانہ نظریہ ہے جو تخلیقی عمل میں خدا کے ہاتھ کو خارج کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ انسان کو، جو محض مادی وجود سے کہیں بڑھ کر ہے، صرف جینز اور ماحول کی پیداوار بنا دیتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ تمام چیزیں ارتقا کو مزید مشکل بنا دیتی ہیں:
یقیناً انسان کی زندگی بندر کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن انسان میں وہ کچھ خصوصیات بھی ہیں جو ہمیں بندر میں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس کائناتی تصور میں کام کریں جہاں صرف مادی دنیا ہی موجود ہے جیسا کہ جدید سائنس دعویٰ کرتی ہے، تو پھر کوئی چارہ نہیں کہ اعلیٰ حیات کو نچلی حیات کا ارتقا مانا جائے اور بالآخر سب کو مادی اجزا تک محدود سمجھا جائے۔ لیکن اگر آپ اس کائنات میں رہتے ہیں جہاں خدا کی منفرد تخلیقی قوت کو مانا جاتا ہے… تو پھر یہ تسلیم کرنا آسان ہے کہ وہی الٰہی قوت کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، زندگی بخش سکتی ہے اور انسانوں کو روح سے نواز سکتی ہے (Nasr 2006, 190–191۔
تاہم ان تمام اعتراضات کے باوجود، ارتقا بنیادی طور پر اس لیے مشکل ہے کہ سید حسین نصر اور عثمان بکر نے ایک Neoplatonic نقطہ نظر اختیار کیا ہے (Bagir 2005, 49)۔ لہٰذا خواہ اس نظریے کے حق میں کتنا ہی سائنسی دباؤ موجود ہو، اور چاہے وہ سائنسی اعتراضات بھی کسی طور حل کر لیے جائیں جو انہوں نے ارتقا پر کیے ہیں، ان کا فکری تناظر اصلاً انواع کی کسی قسم کی تبدیلی کو ماننے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔
مظفر اقبال ، جو ایک کیمیا دان سے متکلم بنے، حسین نصر اور عثمان بکر کی یہی تشویش دہراتے ہیں۔ تاہم مظفر اقبال اسلامی روایت میں رائج نظم کے تصور پر بھی زور دیتے ہیں جو ارتقا کے کے نظریے میں پیش کیے گئے اتفاق پر مبنی تصور کے برعکس ہے۔ ان کے بقول:
ارتقا کے مختلف نظریات کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اتفاق پر انحصار کرتے ہیں، نہ کہ نظم (Design) پر۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انواع (یا ان کے اعضا) کے ظہور میں کوئی ڈیزائن موجود نہیں اور ہر نوع اور ہر عضو تدریجاً کامل ہوتا گیا جیسا کہ ڈارون نے کہا، تو پھر نہ صرف ڈیزائن کو بلکہ اس ڈیزائن کے خالق کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ دکھایا جائے کہ کامل اعضا اور انواع کا اتفاقی ارتقا ان کی پیچیدگی کی وجہ سے ممکن ہی نہیں، تو ڈارون کا نظریہ منہدم ہو جائے گا۔ ڈیزائن کے خلاف دلائل میں عموماً فطرت سے جمع کیے گئے بعض ’’حقائق‘‘ کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ سب حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن جب ان ’’حقائق‘‘ کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں تو یہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ چاہے کتنا ہی باریک تجزیہ کر لیا جائے، بال ہمیشہ بال ہی رہے گا۔ بلاشبہ آج ہماری معلومات جسمانی دنیا کے بارے میں آٹھ سو برس پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر اضافہ مقداری نوعیت کا ہے۔ قرونِ وسطیٰ کے سائنسدان ان حقائق سے ناواقف نہیں تھے جنہیں آج کل کی نئی دریافتیں کہا جاتا ہے۔ صرف ایک ماخذ "کتاب الدلائل" نباتات، حیوانات، انسانی جسمانیات اور نفسیات سے سینکڑوں تفصیلات فراہم کرتی ہے جو ڈیزائن کے تصور کے حق میں بطور دلیل جمع کی گئی ہیں۔ اس روایت سے غایت درجہ کے دلائل لامحدود طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی علمی روایت نہ صرف اس ضرورت سے واقف تھی کہ ڈیزائن کے تصور کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹ کر ایک آزاد دلیل کے طور پر مرتب کیا جائے بلکہ اس نے اسے نہایت باریکی اور تکمیل تک پہنچایا Muzaffar Iqbal (2008; 2009)۔
یہ حیرت کی بات نہیں کہ مظفر اقبال فطرت میں پائی جانے والی پیچیدگی کو بنیاد بنا کر "نظم و حکمت" کے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے Michael Behe اور William Dembski جیسے اہلِ فکر کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں جن کا ذکر ہم باب دوم میں کر چکے ہیں۔
وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کی ایسی تعبیرات جو ارتقا کے حق میں پیش کی جاتی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ خاص طور پر وہ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو قرآن میں آدم کی تخلیق کو استعارہ یا علامتی طور پر بیان کیا ہوا سمجھتے ہیں (Iqbal 2009, 28)۔ اسی طرح وہ اس رویے پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ ارتقا کو قرآن کی کسی ایک آیت میں ڈال کر سمجھنے کی کوشش کی جائے، بغیر اس کے کہ پورے قرآن کو مجموعی طور پر سامنے رکھا جائے (Iqbal 2009, 33–34)۔ مثال کے طور پر یہ آیت دیکھیے:
جبکہ اُس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ (اَطواراً)" (القرآن 71:14)
بعض لوگوں نے اس آیت کو اس بات کے ثبوت کے طور پر لیا ہے کہ قرآن میں ارتقا کا تصور موجود ہے۔ لیکن اس طرزِ فکر پر سخت تنقید کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جامع اور ہمہ گیر نصی شواہد پر مبنی نہیں ہے اور مسلمانوں کے گزشتہ چودہ سو سال کے متفقہ عقائد کے خلاف ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر وہ ارتقا کی کسی بھی دینی تعبیر، مثلاً theistic evolution (جس کا ذکر ہم نے باب دوم میں کیا تھا)، کی صحت پر سوال اٹھاتے ہیں (Iqbal 2010)۔ شیخ معبود بھی اس بحث میں تفسیری پہلو پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن بالکل واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ پودے، جانور اور انسان الگ الگ اور غیر تدریجی تخلیقات ہیں۔ پودوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:
قرآن کے مطابق تمام قسم کے پودے، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی مشابہ کیوں نہ ہوں، الگ الگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی وہ وقت کے طویل عرصے میں ایک دوسرے سے ارتقا پذیر نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو ارتقا کی طرف براہِ راست یا بالواسطہ اشارہ کرتی ہو۔(Mabud 1991, 71)
وہ اپنے مؤقف کے ثبوت میں قرآن کی ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو الگ اور منفرد تخلیقات کے پیدا کیے جانے کو بیان کرتی ہیں۔ مثلاً یہ آیت:
وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور اس میں راستے بنائے، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر قسم کے پودے اگائے۔ (القرآن 20:53)
جانوروں کے معاملے میں بھی شیخ معبود اسی طرح دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی تدریجی تخلیق کا ذکر نہیں۔ یہ ان کے فکری ڈھانچے کا حصہ ہے جس کے مطابق قرآن کو عمومی اور مسلسل طور پر غیر ارتقائی انداز میں سمجھا جانا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں:
اگر ہم حیوانات کی دنیا میں ارتقا کو مان لیں، تو پھر ہمیں انسان کو بھی حیوانی سلسلے کا حصہ ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہوگا… [اسی طرح] جب قرآن نے صراحت کے ساتھ نہ تو یہ کہا ہے کہ انسان ارتقا پذیر ہوا اور نہ یہ کہ پودے ارتقا پذیر ہوئے، تو پھر ہم جانوروں کے معاملے میں ارتقا کو کیوں قبول کریں (Mabud 1991, 73)۔
ایک اور جگہ وہ تخلیقیت کے ایک اور ثبوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جنّات کی مثال دیتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ دھوئیں سے پیدا کیے گئے (القرآن 55:15)۔ اس پر لکھتے ہیں:
یہ ایک بالکل واضح مثال ہے ایسی مخلوق کی جو الگ اور منفرد طور پر پیدا کی گئی، کسی پہلے سے موجود نوع کے ذریعے ارتقا کے عمل سے نہیں بلکہ براہِ راست مادّے سے ایک غیر مسلسل (discontinuous) طریقے سے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی theistic evolution کا حامی جنّات کی اصل کو امیبا سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا (Mabud 1991, 74)۔
چنانچہ شیخ معبود کے نزدیک یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کسی بھی طرح کی تدریجی تخلیق کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ ایک واضح تخلیقیت پر مبنی تصورِ کائنات پیش کرتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ آدمؑ کی تخلیق کو ایک معجزہ مانتے ہیں، جو والدین کے بغیر ہوئی اور جس سے انسان وجود میں آئے۔
شامی سنّی عالم محمد سعید رمضان البوطی بھی نظریہ ارتقا کے سخت ناقد کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کے نزدیک اس نظریے پر دو بنیادی اعتراضات ہیں: ایک نقلی (scriptural) اور دوسرا سائنسی (2017 , 311–342) ۔ سائنسی پہلو سے وہ وہی نکات دہراتے ہیں جو پہلے بھی بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ ارتقا محض ایک نظریہ ہے۔ نقلی پہلو سےالبوطی آدمؑ کی تخلیق کے قصے کو، جس پر باب سوم میں گفتگو ہو چکی ہے، حرفِ آخر مانتے ہیں۔ وہ قرآن میں انسان کی انفرادیت اور شرافت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے:
اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔(القرآن 17:70)
بیشک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔(القرآن 95:4)
البوطی ان آیات کو ایسے دلائل کے ساتھ جوڑتے ہیں جیسے انسانی روح کی انفرادیت اور وہ عقلی صلاحیتیں جو صرف انسان کو حاصل ہیں Al-Būṭī (2017, 314) ۔ مزید برآں، وہ دیگر آیات کا حوالہ دیتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات اور اس کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں:
اور اُس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ سب کچھ اُس کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہے۔ بیشک اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔(القرآن 45:13)
مجموعی طور پر یہ باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان ایک برتر مخلوق ہے، اور اسی بنیاد پر البوطی انسان کی اصل کو ارتقائی عمل سے خارج قرار دیتے ہیں، خصوصاً جب وہ نظریہ ارتقا کو ایک سائنسی نظریہ کے طور پر منفی انداز میں جانچتے ہیں۔
بھارت کے معروف متکلم محمد شِہابُ الدین ندوی نے دعویٰ کیا کہ ارتقا محض ایک افسانہ ہے (1998، ص 20-22)۔ مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ ارتقا دراصل یہودی ذہن کی پیداوار ہے جو ایک خفیہ صیہونی ایجنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں:
سائنس دانوں سے بڑھ کر دہریت کے حامی اور ان کی تنظیمیں نظریہ ارتقا کی پشت پناہی میں سرگرم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ مارکسسٹ، صیہونی اور فری میسن بھی اس کام کو آگے بڑھانے میں پیش پیش رہے۔ یہود ہمیشہ سے مذہب اور مذہبی اقدار کو جڑ سے اکھاڑنے کے خواہاں رہے ہیں۔ دنیا پر حکمرانی کی خفیہ تمنا وہ مدتوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے پروٹوکول اس دیرینہ خواب کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی مقصد نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مذہبی اور اخلاقی اقدار کو ختم کرنے اور تمام الحادی و لادینی عقائد، مادی فلسفوں اور مختلف ”ازموں“ کو فروغ دینے میں سرگرم ہوں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر قوم کی اخلاقی بنیادوں پر کاری ضرب لگانا ضروری ہے۔اگر عالمی فکری منظرنامے پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دو صدیوں میں یہود اس پر حاوی رہے ہیں۔ کارل مارکس، جو مارکسزم کا بانی تھا؛ فرائڈ، جس نے جنسی آزادی کی حمایت کی؛ اور ڈرکھائم، جس نے اجتماعی مادیت کا تصور پیش کیا، یہ سب یہودیوں میں سے اٹھے۔ اگرچہ ڈارون یہودی نہیں تھا، لیکن اس کا نظریہ ارتقا یہودی منصوبے میں بخوبی فٹ بیٹھتا تھا۔ اسی لیے یہود اس کے سب سے بڑے مبلغ بن گئے۔ ڈارون ازم اور مارکس ازم کی ترویج صیہونی ایجنڈے میں اعلیٰ ترین ترجیح کی حیثیت رکھتی تھی اور اسے ان کے پروٹوکول میں بطور لازمی شق شامل کیا گیا (1998، ص 20-24)۔
انہوں نے آدمؑ کی تمثیلی (allegorical) تعبیرات کے خلاف بھی استدلال کیا۔ ان کے نزدیک آدم ایک تاریخی شخصیت ہیں اور قرآن اس حقیقت کو بالکل واضح کرتا ہے ۔ اس کے برعکس کہنا ایسے نتائج کو جنم دیتا ہے جن میں اسلام کے دیگر انبیا کو بھی محض اساطیری حقیقت قرار دینا شامل ہے(ندوی 1998، ص 107–116)۔
ذیل کی آیات پر غور کیجیے جن میں آدم کا ذکر نوح، ابراہیم اور عیسیٰ کے ساتھ آیا ہے:
اللہ نے آدم کو، نوح کو، آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا۔(القرآن 3:33)
بیشک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے: اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ’ہو جا‘ تو وہ ہو گیا۔(القرآن 3:59)
ندوی اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اگر آدم کو تمثیل کے طور پر تعبیر کیا جائے، تو پھر ان آیات میں مذکور دیگر انبیاء کو تمثیل ماننے سے کیا چیز روکے گی؟ آدم کو تمثیل کہنا اور باقی انبیاء کو تاریخی ماننا ایک بے اصول، وقتی اور من مانی تعبیر ہوگی جو فکری تضاد اور عدمِ تسلسل کو جنم دیتی ہے (1998، ص 99–106)۔
آخر میں، ہارون یحییٰ، جو عدنان اوکطار "Adnan Oktar" کا قلمی نام ہے، ایک خود ساختہ ترک مبلغ ہیں جو ارتقا اور اس کی اسلام سے عدم مطابقت پر کئی مشہور کتابیں شائع کرنے کے بعد شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ ان کی کتابوں میں The Atlas of Creation اور The Evolution Deceit (Solberg 2013) شامل ہیں۔
اب تک زیرِ بحث آنے والے تمام مفکرین میں، ہارون یحییٰ ارتقا کو تسلیم نہ کرنے کے سب سے زیادہ متنوع دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ سائنس کو سرے سے رد کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ارتقا کے حق میں دیے جانے والے ہر ثبوت، چاہے وہ فوسل ریکارڈ ہوں ، مالیکیولر بایولوجی ہو یا ہمولوجی "homology" وغیرہ، اپنے معیار پر بار بار ناکام ثابت ہوتے ہیں(Yahya 2001a; 2003a; 2006a)۔ مزید یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ارتقا بذاتِ خود ایک "قدرت پرستانہ" (naturalistic) نظریہ کائنات ہے جو اسلامی زاویہ نظر کے خلاف ہے۔
یحییٰ ارتقا کے فکری ماخذ پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد دراصل یونانی فلاسفہ کے pagan origins سے جڑتی ہے، جہاں زندگی کی ابتدا کو ماورائی یا الوہی تناظر میں نہیں بلکہ خالصتاً مادی اصولوں کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یحییٰ کے نزدیک اس تاریخی تناظر سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ارتقا کا فکری ڈھانچہ ابتداء ہی سے ایک naturalistic worldview پر قائم ہے، جو اسلامی تصورِ کائنات کے ساتھ بنیادی طور پر ہم آہنگ نہیں ہوسکتا۔ اسی لیے وہ واضح طور پر اس امر پر اصرار کرتے ہیں کہ chance-like mechanisms یعنی محض اتفاقیہ عوامل کے ذریعے حیات اور کائنات کی تشکیل، اسلامی عقیدے سے سرِے سے متناقض ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
ایک صاحبِ ایمان مسلمان کے نقطۂ نظر سے جب اس مسئلے پر غور کیا جائے اور قرآنِ حکیم کی تعلیمات کو رہنما بنایا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نظریہ جو اپنی اساس میں chance پر مبنی ہو، اسلامی تصورِ تخلیق کے ساتھ کسی درجے میں بھی ہم آہنگ نہیں ہوسکتا۔ نظریۂ ارتقا کے مطابق زندگی کی تشکیل و ارتقاء میں chance، وقت اور بےجان مادہ فیصلہ کن عناصر ہیں، اور یوں انہیں عملاً خالق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک pagan-based theory ہے جو مادی اور غیر شعوری عوامل کو تخلیقی حیثیت عطا کرتی ہے، اور یہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوسکتی، کیونکہ اسلامی عقیدہ اس بنیاد پر استوار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق ہیں جو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سائنس اور عقل دونوں کو بطورِ آلہ استعمال کرتے ہوئے ہر اس نظریے اور فکر کی تردید کرے جو اس بنیادی ایمانی حقیقت سے متعارض ہو (Yahya 2003b, 33–34)۔
اس نکتے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، ہارون یحییٰ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نظریہ ارتقا دراصل چارلس ڈارون کی اختراع ہے، جو ایک دہریہ تھا۔ ہارون یحییٰ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈارون نے اپنے عدمِ ایمان کو اس لیے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا نظریہ خدا کے انکار کی روشنی میں کسی رکاوٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ یہ پہلو ہارون یحییٰ کے نزدیک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دہریت اور ارتقا کو ایک ہی سکے کے دو رُخ سمجھتے ہیں، اس طرح کہ ڈارون کے نظریے کی حمایت دراصل دہریت کی تائید کے مترادف ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:
حقیقت یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سو برس سے دہریہ مفکرین ڈارون کے حامی رہے ہیں اور لادینی نظریات نے محض اس کی دہریت کی وجہ سے ڈارون ازم کو تقویت بخشی ہے۔ اس لیے ڈارون کے دہریہ ہونے کے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اسے مذہبی یا کم از کم مذہب کے مخالف نہ سمجھیں، اور پھر اس کی ذات، اس کے نظریے یا اس جیسے دوسرے خیالات کی حمایت کرتے رہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو عملاً اپنے آپ کو دہریوں کی صف میں شامل کر لیں گے (Yahya 2003, 54–56)۔
اسی لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہارون یحی نے اپنی بعض تصانیف میں Intelligent Design (ID) کی تحریک سے متعلق لٹریچر سے استدلال کیا ہے۔ مظفر اقبال کی طرح وہ بھی اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے Michael Behe کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہارون یحی کا کہنا ہے کہ ارتقا نے ماضی کے مختلف سماجی و سیاسی "ازموں" کو جنم دینے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔
گزشتہ تقریباً ایک صدی کے فکری و سماجی رجحانات، جن میں کمیونزم، فاشزم، کیپٹلزم اور نسلی امتیاز شامل ہیں، کو ہارون یحیٰ ارتقائی فکر کی پیداوار قرار دیتے ہیں اور اسی کو دنیا میں اخلاقی زوال کا بنیادی سبب بھی بتاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہارون یحی تخلیق پر مبنی قرآنی بیانیے کے مطالعہ پر زور دیتے ہیں اور اس میں ارتقائی تصور کو تلاش کرنے کی کسی بھی کوشش کو رد کردیتے ہیں۔ تاہم یہ پہلو خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اگرچہ وہ ارتقا کے سخت ناقد ہیں، پھر بھی وہ اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو زندگی کو ارتقائی عمل کے ذریعے بھی تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک موجودہ دلائل ،خواہ وہ وحی سے ماخوذ ہوں یا سائنسی تحقیق سے، اس نتیجے تک پہنچنے کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتے (Yahya 2003, 108–109)۔
تخلیق پسند مکتبِ فکر کے اس جائزے کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ اس مختصر بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مختلف مفکرین نے ارتقا کو رد کرنے کے لیے نہایت متنوع دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں کہیں سائنسی دلائل ہیں، کہیں فلسفیانہ و الٰہیاتی استدلال، کہیں تفسیری توضیحات، اور بعض اوقات سماجی و سیاسی بنیادیں بھی۔ بعض نکات پر ان کے افکار میں اشتراک پایا جاتا ہے، مثلاً آدم کی تمثیلی تعبیر کو ناقابلِ قبول قرار دینا؛ جبکہ کئی مواقع پر وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ہی علمی دائرے میں استدلال کرنے والے مفکرین کے مابین بھی زاویۂ نظر اور ترجیحات میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ اہلِ فکر ارتقا کو محض اس بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ یہ صرف "ایک نظریہ" ہے، جیسا کہ ذاکر نائیک؛ جبکہ دیگر، جیسے ہارون یحییٰ، اس کے خلاف سائنسی اعتراضات کا ایک منظم اور تفصیلی مجموعہ پیش کرتے ہیں۔
(جاری)