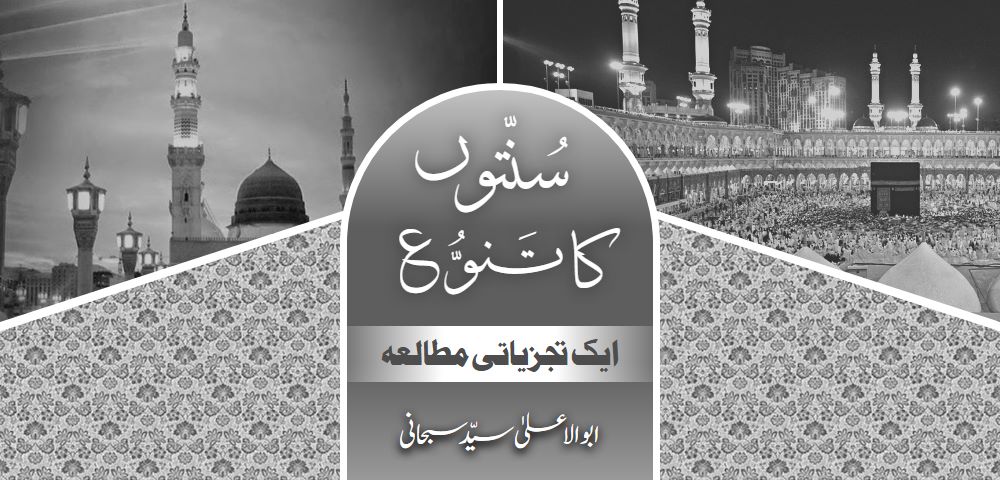امت کے فکرمند اصحاب علم نے ہر زمانے میں امت کو درپیش مسائل کے حل تلاش کرنے کی اپنی اپنی حد تک کی کوششیں کی ہیں، اس سلسلے میں مختلف انداز اور مختلف طریقہ ہائے فکر و نظر رہے ہیں، رائیں بھی مختلف رہی ہیں اور مشورے بھی مختلف رہے ہیں۔ گزشتہ چند صدیوں کا جائزہ لیا جائے تو برصغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ، علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ اور علامہ فراہی علیہ الرحمہ اور ان کے بعد ان کی فکر کے علمبردار اصحاب علم و فکر نے اِس سلسلے میں نمایاں کوششیں کی ہیں۔ بیسویں صدی میں سید مودودی علیہ الرحمہ کا نام امت کے فکرمند اصحاب علم و دانش میں سرفہرست ہے، مولانا سید ابوالاعلی مودودی علیہ الرحمہ کی تحریریں فکرونظر کا ایک وسیع میدان فراہم کرتی ہیں(۱)۔
نماز اتحاد امت کی بنیاد ہے(۲)، تاہم امت اسلامیہ کے اندر موجود اختلافات کی درجہ بندی کی جائے اور ان کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو سرفہرست وہ اختلافات آئیں گے جن کا تعلق نماز سے ہے، یہ صورتحال کا بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ چنانچہ مختلف زمانوں میں امت کے فکرمند اصحاب علم و دانش نے اس پر اپنے اپنے انداز سے کام کیا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلی مودودی علیہ الرحمہ طریقہ نماز سے متعلق اختلافات کے سلسلہ میں بہت ہی واضح نقطہ نظر رکھتے تھے، لکھتے ہیں:
’’اہل حدیث، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی جن جن طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں وہ سب طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہر ایک نے معتبر روایات ہی سے اس کو لیا ہے۔ اسی بنا پر ان میں سے کسی گروہ کے اکابر علماء نے یہ نہیں کہا کہ ان کے طریقے کے سوا جو شخص کسی دوسرے طریقے پر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صرف بے علم لوگوں کا ہی کام ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے طریقے کے سوا دوسرے طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے ملامت کرتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان سب طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس امر میں کہ آپ عموماً کس طریقے پر عمل فرماتے تھے۔ جس گروہ کے نزدیک جو طریقہ آپ کا معمول کا طریقہ ثابت ہوا ہے اس نے وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔‘‘ (۳)
مولانا نہ صرف سنتوں کے تنوع کے قائل ہیں، بلکہ اس تنوع پر عمل کو مستحسن قرار دیتے ہیں اور اس پر نکیر کو اتباع پیغمبر پر نکیر قرار دیتے ہیں:
’’لیکن یہ واضح رہے کہ سوال صرف ترجیح کا ہے نہ کہ رد و قبول کا۔ ائمہ سلف میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جن مختلف طریقوں کا ذکر مذکورہ بالا احادیث میں آیا ہے ان میں سے کسی پر حضور نے عمل نہیں کیا تھا۔ بلکہ کہتے صرف یہ ہیں کہ جس خاص طریقہ کو ہم نے مرجح قرار دیا ہے وہ حضور کا عام معمول تھا اور دوسرے طریقوں پر آپ کبھی کبھی عمل کر لیتے تھے۔ پس جب معاملہ کی حقیقت یہ ہے تو ان طریقوں میں سے جس پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے، حدیث ہی کی پیروی کر رہا ہے اور اس پر نکیر کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اتباع پیغمبر پر نکیر کی جاتی ہے جس کی جرأت مقلدین کو بھی زیبا نہیں کجا کہ اہل حدیث اس کا ارتکاب کریں۔ پھر اگر کوئی شخص ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر جامد ہونے کے بجائے وقتاً فوقتاً ان سب طریقوں پر عمل کرتا رہے جو حدیث میں مذکور ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحیح و مکمل پیروی ہوگی، اور لفظ عمل بالحدیث کا اطلاق اس طرز عمل پر زیادہ صحیح معنی میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابتداء ہی میں ایک طریقہ کو ترجیح دینے اور باقی سب طریقوں کو ترک کر دینے کے بجائے ان سب طریقوں کو نماز میں اختیار کرنے کی گنجائش رکھی جاتی تو شاید بعد کے ادوار میں وہ جمود و تعصب پیدا ہی نہ ہوتا جس کی بدولت نوبت یہ آگئی ہے کہ لوگ نماز کی جس صورت کے عادی ہیں اس سے ذرا بھی مختلف صورت جہاں انہوں نے دیکھی اور بس وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس شخص کا دین بدل گیا ہے اور یہ ہماری امت سے نکل کر دوسری امت میں جا ملا ہے‘‘۔(۴)
فقہی مسالک کے سلسلے میں بھی مولانا سید ابوالاعلی مودودی علیہ الرحمہ نے اسی پہلو سے گفتگو فرمائی ہے۔(۵)
مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے پہلے بھی سنتوں کے تنوع پر مختلف اہل علم نے اپنے اپنے انداز سے قلم اٹھایا ہے، اس ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت قابل ذکر ہے، پروفیسر محمد یٰسین مظہر صدیقی اپنی کتاب ’’سنتوں کا تنوع‘‘ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:
’’دوسرے صاحبان فکروبصیرت کی مانند حضرت شاہؒ نے بھی سراغ لگایا کہ ہر مسلک و فکر کی بنیاد کسی نہ کسی اصل بلکہ مضبوط اصل (اصل اصیل) پر قائم ہے۔ انہوں نے ’’اصل السنۃ‘‘ اور اس کی وجوہ اور شکلوں کی سب سے زیادہ وضاحت کی۔ ظاہرِ حدیث اور مجموعی تناظر میں حدیث و سنت کا بنیادی فرق جانا اور واضح کیا۔ فقہی اختلافات کی دوسری وجوہ کو بھی خوب بیان کیا۔ وہ ترجیح دینے کے بھی قائل ہیں اور مختلف احادیث و سنن میں تطبیق دینے کے تو امام ہیں۔ اسی بنا پر وہ فقہی خلیج کو پاٹ کر امت میں اتحاد فکروعمل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔‘‘(۶)
پروفیسر محمد یٰسین مظہر صدیقی علم و تحقیق کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، موصوف کی زندگی علم و تعلیم اور تصنیف و تحقیق سے عبارت ہے، یقینا شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خدمات کا تذکرہ موصوف کے ذکر ِخیر کے بغیر نامکمل رہے گا۔ پروفسیر یٰسین مظہر صدیقی کی کتاب ’’سنتوں کا تنوع۔ ہر سنت نبوی افضل ہے‘‘ اپنے موضوع پر ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ یہ کتاب سنتوں کے تنوع سے متعلق شاہ ولی اللہ اور سید مودودی (۷)کے نقطہ نظر کو مفصل انداز میں پیش کرنے والی پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔
مقدمہ کتاب میں مصنف موصوف لکھتے ہیں:
’’مجتہدین کے اجتہادِ خالص پر مبنی ہوں یا متنوع و مختلف احادیث و سنن پر قائم ہوں، تمام فقہی و مسلکی اختلافات بنیادی طور سے کتاب و سنت ہی پر محمول کیے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تمام اماموں نے مختلف سنتوں ہی میں سے کسی نہ کسی سے تمسک کیا ہے اور اسی پر اپنی فقہی فکروعمل کی بنیاد رکھی ہے‘‘۔(۸)
آگے لکھتے ہیں:
’’مختصراً یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ رسول اکرمؐ نے کبھی ایک وجہِ سنت پر عمل فرمایا یا ایک جہتِ حدیث بیان فرمائی اور کبھی دوسری، بسا اوقات ان کی کئی کئی وجوہ وجہات ملتی ہیں۔ اور نہ صرف ان رنگارنگ سنتوں پر بنفس نفیس عمل فرمایا بلکہ ان ہی کی تعلیم صحابہ کرام کو الگ الگ دی۔ کسی کو ایک وجہِ سنت سکھائی اور کسی کو دوسری، کسی اور صحابی کو تیسری اور بسا اوقات یہ تعداد دس بارہ سے بھی تجاوز کر گئی۔ ہر صحابی نے اپنی سیکھی ہوئی سنت پر عمل کیا اور دوسرے صحابہ کو وہی سکھائی اور دوسرے مسلمانوں اور شاگردوں کو اسی خاص سنت کی تعلیم دی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ایک ہی معاملہ سے متعلق نوع بہ نوع سنتیں رواج پا گئیں اور سنتوں کا یہی تنوع تابعین کرام کو ورثہ میں ملا اور ان سے بعد کے لوگوں کو اور امامانِ فقہ اور مجتہدین امت نے اپنے اپنے شیوخ و اساتذہ کے واسطے سے صحابہ کرام اور ان کے ذریعہ سنن نبوی کا تنوع پایا۔ روایت و درایت کے اعتبار سے کس کا کیا پایہ ہے اس کا تعلق فن حدیث و سنت سے ہے اور خالص تکنیکی ہے۔ رسول اکرم ؐ کی ہر ثابت شدہ حدیث و سنت نہ صرف ہم پلہ وہم سر ہے بلکہ ہر ایک افضل و اصح اور صحیح ترین ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ سنت نبوی ہے۔ ‘‘(۹)
آگے مزید لکھتے ہیں:
’’اس مختصر کتاب کا مقصود صرف اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ رسول اکرمؐ کی ہر سنت افضل و صحیح ترین ہے‘‘۔ (۱۰)
کتاب کا بڑا حصہ نماز کی متنوع سنتوں پر مشتمل ہے، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’طہارت کے مختصر باب یا بحث کے بعد سارا زور نماز کی متنوع سنتوں پر ہے کہ ان ہی میں تفرقہ بازی زیادہ کی جاتی ہے۔ اپنی پسندیدہ یا مختار وجہِ سنت کو واحد و مستقل سنت بتایا جاتا ہے اور دوسرے یا دوسروں کی پسندیدہ یا مختار سنتوں کو ہر طرح سے کمزور، ضعیف، اعتبار سے ساقط، ناقابل عمل حتی کہ غلط بتایا جاتا ہے۔ یہ علمی یا اسلامی اندازِ فکر ہے اور نہ حدیثی تشریح و تعبیر۔ یہ خالص مسلکی جارحیت اور فقہی عصبیت ہے جو مردود ہے۔ صرف سلسلہ کلام کو منطقی انداز میں ختم کرنے کی خاطر دوسرے ابواب زکوۃ و صدقہ، روزہ و حج جیسی عبادات میں بھی بعض سنتوں کا تنوع واضح کیا گیا ہے‘‘۔(۱۱)
کتاب کی تمہید کے اختتام پر دوٹوک انداز میں لکھتے ہیں:
’’اصل مقصد تو یہ بتانا ہے کہ سنتوں میں تنوع پایا جاتا ہے اور ان رنگارنگ سنتوں میں سے کسی پر بھی عمل ہو جائے اجروثواب، تقویٰ و طہارت اور تزکیہ و تعلیم سب کے لیے کافی شافی ہے۔‘‘ (۱۲)
مصنف کی یہ فکر بہت اہم ہے کہ جو سنتیں ثابت ہیں وہ سب افضل ہیں۔ اور ان میں کسی بھی سبب سے ترجیح دینا مناسب نہیں ہے۔ لکھتے ہیں:
’’انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اپنی پسندیدہ اور مختار سنت نبوی کو راجح قرار دینے اور دوسری غیر مختار سنت کو مرجوح قرار دینے کا کوئی جواز ہے نہ بنیاد، اس کی فقہی اور حدیثی وجہِ ترجیح بھی نہیں ملے گی‘‘۔ (۱۳)
مزید لکھتے ہیں:
’’اصل سنت نبوی یہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے ان تمام متنوع اور رنگ برنگی سنتوں پر خود بھی عمل فرمایا اور مختلف صحابہ کرام کو الگ الگ سنتیں ایک مسئلہ و معاملہ پر سکھائیں، لہٰذا وہ سب کی سب برابر فضیلت رکھتی ہیں‘‘۔ (۱۴)
کتاب کے آخر میں نتیجہ بحث کے طور پر بہت ہی قیمتی بات لکھتے ہیں:
’’تمام بحث و مباحثہ اور تجزیہ و تنقید کا خالص اصولِ فکری اور اسوۂ عمل یہ نظر آتا ہے کہ تمام مسالکِ فقہ اور طبقات فکر اپنی اپنی اختیار کردہ سنتوں کو ہی مانیں اور ان کو افضل سمجھ کر ان پر عمل کریں اور ان کی تعلیم و اشاعت بھی خوب کریں۔ اب رہیں دوسروں کی اختیار کردہ سنتیں تو ان کے لیے رسول اکرمؐ کا اصول و عمل اختیار کریں کہ وہی اصل الاصول ہے۔ رسول اکرمؐ نے جب الگ الگ سنتیں صحابہ کرام اور ان کے ذریعہ مختلف طبقات صحابہ کو سکھائیں تو آپؐ کا مقصود ہی یہی تھا۔ وہ واضح کرتا ہے کہ تمام سنتیں افضل ہیں۔ رسول اکرمؐ بھی ان کو افضل و اصح سمجھتے تھے اور آپؐ کے صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ ‘‘(۱۵)
آگے ایک بہت ہی قیمتی اور عملی بات لکھتے ہیں:
’’فکروعمل نبوی سے ہی صحابہ کرام نے سیکھا تھا کہ وہ اپنی اپنی اختیار کردہ سنتوں کو افضل سمجھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے صحابہ کرام کی اختیار کردہ سنتوں کو بھی افضل ہی سمجھتے تھے اور ان پر عمل کرنے والوں پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کی بھی تحسین و تعریف کرتے تھے۔ یہی روِش علماء تابعین اور ائمہ مجتہدین کی بھی رہی، اور متعدد محدثین اور دوسرے اکابر کی بھی رہی۔ ‘‘(۱۶)
کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف موصوف کی تحقیق کا نتیجہ اور نتیجے کے پیچھے کارفرما محرک بہت ہی اعلی اور بلند ہے، یہ نکتہ بہت ہی اہم ہے کہ جو سنتیں ثابت ہیں وہ سب افضل ہیں اور ان میں کسی بھی سبب سے کسی کو کسی پر ترجیح دینا یا کسی کو کسی سے افضل قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن سنت ثابت کیسے ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب کافی و شافی رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ نماز کے طریقوں سے متعلق اختلافات کی ایک بڑی بنیاد یہی ہے کہ طریقہ نماز سے متعلق یہ اور یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اور ان سے متعلق روایات کمزور اور غیر معتبر ہیں، اور بعض اعمال جیسے خواتین کی نماز کے مختلف طریقوں سے متعلق تو سرے سے کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں، ایسی صورت میں سنتوں کے تنوع کی پوری بحث پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔
پوری کتاب میں سنت بمعنی طریقہ رسول اور سنت بمقابلہ واجب و فرض کے درمیان بھی بہت زیادہ خلط مبحث پایا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں:’’ بہت سی سنتیں ایسی بھی ہیں جو فرض و واجب کی مانند صرف ایک رخ یا صرف ایک جہت رکھتی ہیں‘‘(۱۷)، حالانکہ تنوع تو فرض میں بھی ہو سکتا ہے جیسے تیمم فرض ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں اور وہ سب فرض کے درجے کے ہیں۔
عام طور سے سنتوں کے تنوع میں احادیث کو دلیل بنایا گیا ہے، لیکن احادیث میں بہت سی ناقابل استناد روایتیں ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ باندھنے کی سنتیں، لکھتے ہیں کہ ’’مولانا سیالکوٹی نے حسب دستور مسلک صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث کو صحیح کہا ہے اور اسی کو واحد سنت قرار دیا ہے، بقیہ تمام احادیث و روایات کو ضعیف قرار دے کر ان سے استدلال کو غلط بتایا ہے‘‘۔ (۱۸)
چونکہ مصنف حدیث اور سنت کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے عملی تواتر کی دلیل پوری کتاب میں محض کہیں کہیں اور وہ بھی مختصر اشاروں کی صورت میں نظر آتی ہے، اس کو باقاعدہ استدلال کے طور پر کہیں نہیں پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ باندھنے کی سنتوں سے متعلق مولانا سیالکوٹی کا موقف پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
’’ان سنتوں کے تنوع کے باب میں ایک اور اہم حقیقت یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ محدثین کرام اور ان سے پہلے ائمہ مجتہدین نے اپنے زمانے کے صحابہ و تابعین اور امت کے دوسرے طبقات میں ان مختلف و متنوع سنتوں کے جاری ہونے کا عمل بھی دیکھا تھا۔ ان کا انحصار صرف روایت پر نہیں تھا۔ امام مالکؒ موطا میں جابجا اپنے اہل شہر اور اکابر مدینہ کے دستور و عمل کو سنت کی بنیاد بناتے ہیں، اور یہی دوسرے اکابر کا وطیرہ ہے۔‘‘ (۱۹)
لیکن آگے چل کر پھر اپنے پرانے ہی موقف کو دوہراتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’بہرحال احادیث کے مطابق تینوں طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا سنت کی پیروی کرنا ہے‘‘۔(۲۰)
مصنف حدیث میں عملی تواتر کو شامل کرتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت کتاب میں کہیں موجود نہیں ہے۔ حدیث سے احکام اسلامی کے ثبوت سے متعلق مصنف کی گفتگو اس سلسلے میں وضاحت طلب ہے، لکھتے ہیں:
’’نماز پنجگانہ کے اوقات، نمازوں کی رکعات، ان کی ہیئت، ارکان، فرض و واجب، مسنون و مستحب احکام صرف حدیث پر مبنی ہیں‘‘۔ (۲۱)
مذکورہ عبارت میں مصنف موصوف اگر حدیث میں عملی تواتر کو شامل سمجھتے ہیں تو بات درست ہو سکتی ہے، بصورت دیگر یہ بات کسی بھی طور درست نہیں ہے۔
گزشتہ دنوں ڈاکٹر محی الدین غازی کی کتاب ’’نماز کے اختلافات اور ان کا آسان حل‘‘ پر کافی بحث و مباحثے ہوئے، موصوف بھی سنتوں کے باب میں تنوع کے قائل ہیں اور سنتوں کے درمیان کسی قسم کی ترجیح یا تفاضل کو وہ بھی درست نہیں مانتے، تاہم دونوں کے موقف کے درمیان سب سے واضح اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر محی الدین غازی کے ہاں عملی تواتر سنتوں کے تنوع کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی بنیاد ہے، جو سنتوں کے تنوع پر ہونے والے تمام ہی اعتراضات کا ازخود ازالہ کر دیتی ہے، جبکہ پروفیسر یٰسین مظہر صدیقی صاحب سنتوں کے تنوع کی بنیاد سنتوں کے ثبوت کو قرار دیتے ہیں۔
ڈاکٹر محی الدین غازی اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’نماز کے مختلف اعمال کا تذکرہ مختلف راویوں نے کیا، یہ تذکرے ہم تک حدیث کی کتابوں میں مدون ہو کر راویوں کے الفاظ کی صورت میں پہنچے، ان تذکروں کی حیثیت قولی روایت کی ہے، قولی روایتوں میں تواتر شاذ و نادر ہی ملتا ہے، زیادہ تر اخبار آحاد ہیں، جن میں کچھ روایتیں صحیح ذریعہ سے پہنچی ہیں اور کچھ کمزور ذریعہ سے، تاہم جو حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ کہ امت نے نماز پڑھنی ان قولی روایتوں سے نہیں سیکھی، بلکہ ان روایتوں سے پہلے اور ان روایتوں کے بغیر سیکھی اور ان متواتر عملی روایتوں کے ذریعہ سیکھی، جن کی حیثیت متواتر عملی سنت کی ہے، قولی روایتیں تو بسا اوقات ایک راوی سے ایک دو راویوں تک پہنچیں، مگر نماز ساری امت سے ساری امت تک پہنچی، گویا امت نے نماز راویوں سے نہیں سیکھی بلکہ نمازیوں سے سیکھی جن میں یہ راوی بھی شامل تھے۔ جب ہم نماز کے مختلف اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں، بعض اعمال وہ ہیں جن کے سلسلے میں روایتیں بھی آئی ہیں اور عملی تواتر بھی موجود رہا ہے، ساری روایتیں بڑے اعلی درجے کی ہیں اور عملی تواتر تو ہے ہی نہایت اعلی درجے کی دلیل، جیسے تشہد کی مختلف صورتیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جن کے سلسلے میں روایتیں نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت ہی ضعیف ہیں ، البتہ عملی تواتر ہے، جیسے رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ اور عورتوں کے سجدے کی شکل کیا ہو؟ بعض اعمال وہ ہیں جن کے سلسلے میں روایتیں ہیں لیکن ان میں ذرا سی کمزوری ہے، یا یہ کہ وہ خود محدثین کے یہاں معروف نہیں ہیں، تاہم عملی تواتر موجود ہے، جیسے حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں۔ غرض یہ کہ روایتوں کا درجہ مختلف ہو سکتا ہے، کسی عمل کے سلسلے میں متواتر روایتیں مل جاتی ہیں، اور کسی عمل کے سلسلے میں متواتر روایتیں نہیں ملتی ہیں، کسی عمل کے حق میں صحیح روایتیں ملتی ہیں اور کسی عمل کے سلسلے میں ضعیف روایتیں ہی ملتی ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ عظیم فقہاء نے اپنے زمانے میں امت کو نماز کے مختلف اعمال انجام دیتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے جو طریقہ ان کو زیادہ پسند آیا اس کو اختیار کیا، ان کے زمانے میں امت میں جو طریقے رائج تھے، وہ دراصل عملی تواتر کے ساتھ ان کے زمانے تک پہنچے تھے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ہمارا رویہ نماز سے متعلق روایتوں کے بارے میں تبدیل ہونا چاہئے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ نماز بس وہ ہے جو روایتوں میں مذکور ہے ، بلکہ نماز تو پہلے نمبر پر وہ ہے جو امت نے امت کے تعامل سے سیکھی، یعنی جو کچھ صحیح روایتوں میں ہے وہ تو درست ہے، ساتھ ہی وہ جو روایتوں میں نہیں ہے مگر امت نے امت کے تعامل سے سیکھا ہے وہ بھی درست ہے۔‘‘(۲۲)
سنتوں کے تنوع سے متعلق جب عملی تواتر کی دلیل پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ نماز کے مختلف طریقوں سے متعلق یا نماز کی صورت گری کے سلسلہ میں ائمہ مجتہدین کا کیا رول تھا، انہوں نے اس سلسلے میں ازسرنو اجتہاد سے کام لیا جیسا کہ زندگی کے دوسرے مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا یا ان کا کام خالص تدوینی نوعیت کا تھا۔ چونکہ عملی تواتر کی دلیل پروفیسر صدیقی کے ہاں بہت واضح نہیں ہے، اس لیے وہ اس قسم کے سوالات سے بھی تعرض نہیں کرتے، البتہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محی الدین غازی نے بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے، لکھتے ہیں:
’’ائمہ مجتہدین نے امت کو نماز پڑھنا نہیں سکھائی بلکہ اپنے وقت کی امت سے نماز پڑھنا سیکھی، اس یقین کے ساتھ کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور اسی طریقے کی تدوین کی، ہر امام نے جب شعور کی عمر کو پہنچ کر آنکھوں سے دیکھا تو اپنے شہر کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پایا کہ ان کی نماز بالکل درست ہے اور طریقہ رسول کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے زمانے میں امت کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اس لیے ہر امام نے اپنے پاس موجود دلائل کی روشنی میں نماز کا طریقہ امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ اماموں کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے، امت تو ان سے پہلے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ روزانہ نماز پڑھتی تھی، اور پوری امت نماز کے مختلف طریقوں کے بارے میں یہ یقین رکھتی تھی کہ یہ سب طریقے درست ہیں، اور سنت رسول کے مطابق ہیں۔ ان کے درمیان نماز کے طریقوں کو لے کر نہ کوئی بے اطمینانی تھی، نہ کوئی آپس میں جھگڑا تھا۔ اس دور کے اماموں اور فقیہوں نے نماز کے بارے میں یہ کام ضرور کیا کہ نماز کے رائج طریقوں کو ریکارڈ کر لیا۔ چونکہ انہوں نے اس فقہ کی تدوین کا بیڑہ اٹھایا تھا جو لوگوں کی پریکٹس میں تو تھی لیکن ابھی اس کی باقاعدہ تدوین کا عمل تشنہ تکمیل تھا، اور یوں نماز کے سارے طریقے بھی تدوین کے عمل میں شامل ہوگئے۔‘‘ (۲۳)
اس سلسلے میں دوسرا اہم سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ احادیث کی عدم موجودگی میں نماز کا کوئی طریقہ عملی تواتر سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے، یا یہ سوال کہ احادیث کے بغیر عملی تواتر کا وجود کیسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ’’سنتوں کا تنوع‘‘ کتاب میں نہیں ملتا، جبکہ ڈاکٹر محی الدین غازی نے اس سوال پر بھی اچھی گفتگو کی ہے، لکھتے ہیں:
’’احادیث کے نہ ہوتے ہوئے بھی عملی تواتر سے نماز کا کوئی طریقہ کیسے ثابت ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز کیسی ہو؟ یعنی مردوں کی طرح ہو یا ان سے کچھ مختلف ہو۔ رکوع اور سجدہ کے سلسلے میں امت کا عام موقف یہ رہا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلووں سے الگ رکھے، یعنی ہاتھوں اور پسلیوں میں واضح سا فاصلہ رہے، اس کو تجافی کہا جاتا ہے، امام نووی کا کہنا ہے کہ اس عمل کے پسندیدہ ہونے میں کسی بھی عالم کا اختلاف میں نہیں جانتا، اور اس طریقہ میں حکمت یہ ہے کہ یہ نماز کی صورت و ہیئت کے کمال میں اضافہ کرتا ہے۔ امام طحاوی بھی اس بات پر اجماع ذکر کرتے ہیں، متعدد صحابہ سے اس عمل کا مطلوب و مسنون ہونا منقول ہے۔ لیکن یہ سب مردوں کے سلسلے میں ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں صورتحال بالکل مختلف ہے، چاروں فقہی مسالک اس پر تقریباً متفق ہیں، احناف مالکیہ شافعیہ حنابلہ سب کے یہاں یہی رائے پائی جاتی ہے، کہ عورت نماز کے دوران اپنے آپ کو سمیٹے، سجدہ میں اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا لے، پیروں کو کھڑا کرنے کے بجائے، زمین پر چت رکھے، بیٹھے تو تربع کی حالت بنا کر بیٹھے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان سارے ہی مسالک کا موقف ایک ہے اور دلیل بھی ایک ہے، اور وہ دلیل کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف بتائی جاتی ہیں، جس دلیل کو فقہاء ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں عورت کے اعضاء کی پردہ داری زیادہ بہتر طور سے ہوتی ہے، اگر وہ مرد کی طرح رکوع اور سجدہ کرے تو ستر کا پہلو متأثر ہوتا ہے۔ مجھے اس مسئلہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے جس چیز نے بہت متأثر کیا وہ یہ کہ اس بات کے حق میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے مختلف طریقہ اپنائیں ، علامہ البانی نے اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ کہا ہے، کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی وارد ہوا ہے اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہ ہونے کے باوجود چاروں مسلک ایک بات پر متفق ہوگئے، حالانکہ متعدد مسائل میں بہت ساری صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان میں کافی اختلاف ہو رہا ہے۔‘‘(۲۴)
کتاب کے استدلالی پہلو سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ باتیں تحقیقی پہلو سے متعلق بھی توجہ طلب ہیں۔ تحقیقی پہلو سے متعلق کچھ اہم چیزیں تو وہ ہیں جن کی جانب جناب مجاہد شبیر فلاحی صاحب نے سہ ماہی تحقیقات اسلامی (جولائی تا ستمبر ۲۰۰۸ء) میں شائع اپنے تبصرے میں توجہ دلائی ہے(۲۵)۔ اس کے علاوہ بھی متعدد چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
ص ۶۰ پر حافظ ابن حجر کے حوالے سے ایک بات کہی گئی ہے، جبکہ یہ بات حافظ ابن حجر کی نہیں ہے، امام ترمذی کی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں: ’’حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تشہد کو تمام تشہدات میں سب سے صحیح قرار دیا ہے: ان کا بیان ہے کہ تشہد کے باب میں وہ سب سے صحیح حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے اور صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، … وھو اصح حدیث روی فی التشہد والعمل علیہ عند اکثر اھل العلم من الصحابۃ ومن بعدھم‘‘۔
جبکہ سنن ترمذی میں صاف طور پر امام ترمذی کا یہ قول موجود ہے:
’’حدیث ابن مسعود قد روی عنہ من غیر وجہ وھو اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد‘‘، والعمل علیہ عند اکثر اھل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن بعدھم من التابعین، وھو قول سفیان الثوری، وابن المبارک، واحمد، واسحاق۔ (۲۶)
حضرت ابن مسعود کی حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے۔ وہ تشہد کے باب میں سب سے صحیح حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے۔ اسی پر عمل رہا ہے اصحاب علم کے نزدیک، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں، یا ان کے تابعین ہوں، سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔
فتح الباری میں بھی صاف طور سے اس قول کی نسبت امام ترمذی کی طرف کی گئی ہے:
قال الترمذی حدیث بن مسعود روی عنہ من غیر وجہ وھو اصح حدیث روی فی التشہد والعمل علیہ عند اکثر اھل العلم من الصحابۃ ومن بعدھم۔ (۲۷)
ترمذی نے کہا ہے، ابن مسعود کی حدیث ایک سے زائد طرق سے آئی ہے، تشہد کے باب میں وہ سب سے صحیح حدیث ہے۔ اسی پر اہل علم کا عمل رہا ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں، یا بعد کے اہل علم ہوں۔
یہ پہلو اس لیے بھی قابل توجہ ہے کہ مصنف نے اس کی بنیاد پر پوری ایک بحث کھڑی کی ہے، اور اسے ابن حجر کا قول مانتے ہوئے کتاب کے کئی مقامات پر اس کو نقل کیا ہے۔راقم کا خیال ہے کہ فتح الباری میں گرچہ امام ابن حجر نے یہ قول امام ترمذی کی طرف منسوب کرتے ہوئے درج کیا ہے، تاہم پروفیسر موصوف نے سہواً اسے ابن حجر کا قول سمجھتے ہوئے نقل کر دیا ہے۔
اسی طرح کا ایک سہو تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کے مسئلہ سے متعلق بھی ہوگیا ہے، صفحہ ۴۷ پر لکھتے ہیں:
’’امام ابوحنیفہؒ وغیرہ تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کی احادیث و آثار کو قبول کرنے کے باوجود اس کے قائل ہیں کہ یہ پہلے کی سنت تھی اور بعد میں آپؐ نے رفع یدین ترک کر دیا تھا‘‘۔
راقم کی تحقیق کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس رائے کی نسبت کسی بھی طرح درست نہیں ہے، یہ بات احناف کے ہاں متأخرین فقہاء کے ہاں تو ملتی ہے لیکن امام ابوحنیفہ ؒکی طرف نسبت کے ساتھ یہ رائے کہیں نہیں ملتی۔ راقم کا خیال ہے کہ متأخرین فقہاء احناف کی رائے کو پروفیسر موصوف نے امام ابوحنیفہ کی رائے محمول کرتے ہوئے نقل کر دیا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بالکل ہی مختلف ہے۔
چیزوں کو نقل کرنے میں یہ بے احتیاطی کتاب میں اور بھی کئی جگہ کھٹکتی ہے، صفحہ ۱۴۲ پر صحابہ کرام کے اپنی خاص سنتوں اور تعلیم نبوی سے شرعی جذباتی لگاؤ اور بیکراں عشق کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے لکھتے ہیں:
’’حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول اکرمؐ کی خاص تعلیم اور آپؐ کے دہن مبارک سے سن اور یاد کر کے صرف ستر سورتیں ہی اپنے مصحف میں لکھی تھیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں‘‘۔
یہ بات کسی بھی طور پر ناقابل تسلیم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی خاص سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت سے زیادہ عزیز ہو جائے گی، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی شخصیت اور عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر غور کیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے بارے میں یہ بات کہنا کسی بھی طرح سے درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے حوالہ سے اس قسم کی باتیں مختلف کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، حالانکہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں حد درجہ احتیاط، سنجیدگی اور ذمہ داری کا رویہ اختیار کیا جائے۔
کہیں کہیں مسائل کی نوعیت کے تعین میں بھی یہ سہو صاف نظر آتا ہے، صفحہ ۴۳ پر سورہ فاتحہ کی قرأت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’سورہ فاتحہ کی قرأت کا مسئلہ سنت اور اس کے تنوع سے زیادہ فرض و واجب ہونے سے ہے۔‘‘
حالانکہ سورہ فاتحہ کی قرأت سنت ہو یا واجب، یا بعض احوال میں کچھ کے نزدیک اس کا نہیں پڑھنا سنت ہو، یہ سب کچھ سنت ہی کا مسئلہ ہے اور سنتوں کے تنوع کے تحت ہی اس کا صحیح حل مل سکتا ہے، بشرطیکہ عملی تواتر کی دلیل سامنے رہے۔ فعل اور ترک فعل دونوں کا تعلق سنت کے تنوع سے ہے، البتہ فعل کا حکم تکلیفی کیا ہے اور ترک کا حکم تکلیفی کیا ہے اس طرح کے فقہی احکام کا تعلق فقہاء کے اجتہادی اصولوں اور ان کی تطبیق سے ہے۔
صفحہ ۷۸۔۷۹ پر موکدہ سنتوں کا بیان ہے، اور یہاں صاف طور سے سنتوں کے تنوع کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’ان موکدہ سنتوں میں ظاہر ہے کہ تنوع کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بارہ رکعتوں کی تعیین رسول اکرمؐ نے کی ہے۔ مسلم کی حدیث عائشہؓ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ بنفس نفیس بالعموم بارہ رکعت سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ بخاری مسلم کی حدیثِ ابن عمر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں: ’’صلیت مع رسول اللہ ﷺ رکعتین قبل الظھر‘‘۔ اگرچہ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور سند و روایت کے لحاظ سے قوی تر تاہم وہ ایک عارضی اجازت دیتی ہے، عام اصول سنت نہیں بیان کرتی۔ اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ ظہر کے فرض سے پہلے کی چار سنتیں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو دو سنتیں ہی ادا کر لے۔ یہ سنت نبوی ہے محض جائز نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، البتہ خاص احوال کی سنت ہے۔ اس کا ذکر اصل مستقل سنت اور عارضی سنت کے ذیل میں آتا ہے اور اس ضمن میں بھی کہ سنت موکدہ کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے‘‘۔
یہ پوری بات ہی محل نظر ہے، کیونکہ موکدہ سنتوں میں بھی صاف طور پر تنوع موجود ہے، اسی لیے شوافع اور حنابلہ کے یہاں ظہر سے پہلے دو رکعتیں، احناف کے یہاں چار رکعتیں اور مالکیہ کے یہاں عدد معین نہیں ہے۔
عن عبد اللہ بن عمر: أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظھر رکعتین، وبعدھا رکعتین، وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ، وبعد العشاء رکعتین، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف، فیصلی رکعتین۔ (۲۸)
(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور دو رکعتیں ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر پر پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ گھر واپس آجاتے تھے اور پھر دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔)
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، قال: حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر رکعات رکعتین قبل الظھر، ورکعتین بعدھا، ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، ورکعتین قبل صلاۃ الصبح۔ (۲۹)
(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں، دو رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں ظہر کے بعد، اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اور دو رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اور دو رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔)
حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنے موقف پر اعتماد قابل لحاظ ہے۔ یہ عارضی سنت کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک معمول ہے، جبکہ دوسرا معمول حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے، اور دونوں ہی امت میں بطور سنت متواترہ رائج ہیں۔
عن عبد اللہ بن شقیق، قال: سألت عائشۃ عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن تطوعہ؟ فقالت: کان یصلی فی بیتی قبل الظھر أربعا، ثم یخرج فیصلی بالناس، ثم یدخل فیصلی رکعتین، وکان یصلی بالناس المغرب، ثم یدخل فیصلی رکعتین، ویصلی بالناس العشائ، ویدخل بیتی فیصلی رکعتین، وکان یصلی من اللیل تسع رکعات فیھن الوتر، وکان یصلی لیلا طویلا قائما، ولیلا طویلا قاعدا، وکان اذا قرأ وھو قائم رکع وسجد وھو قائم، واذا قرأ قاعدا رکع وسجد وھو قاعد، وکان اذا طلع الفجر صلی رکعتین۔(۳۰)
(حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول پاکؐ کی نفل نمازوں کے بارے میں دریافت کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ میرے گھر میں ظہر سے قبل چار رکعتیں پڑھتے، پھر باہر جاکر لوگوں کی امامت فرماتے، پھر اندر آکر دو رکعتیں پڑھتے۔ مغرب میں لوگوں کی امامت کرنے کے بعد گھر آجاتے اور دو رکعتیں پڑھتے۔ عشاء میں لوگوں کی امامت کرتے، پھر اندر آکر دو رکعتیں ادا کرتے۔ اور آپ رات میں نو رکعتیں پڑھتے جن میں وتر بھی شامل ہوتی، آپ رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کھڑے ہو کر۔ اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے بیٹھ کر۔ کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتے تو رکوع و سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور بیٹھ کر اگر قرآن پڑھتے، تو رکوع و سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے۔ اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو رکعتیں پڑھ لیتے۔)
سنن موکدہ کے تعلق سے پوری گفتگو میں مصنف موصوف کا جھکاؤ ایک خاص مسلک کی طرف نظر آتا ہے ، جبکہ عملی تواتر کی روشن دلیل یہاں صاف طور سے نظرانداز کر دیتے ہیں۔
زبان و بیان کے حوالہ سے بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو کتابت کی غلطی پر محمول کی جا سکتی ہیں، تاہم کچھ باتیں ایسی ہیں جو دعویٰ کے انداز میں کہی گئی ہیں اور ذہن کسی بھی طور پر انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، صفحہ ۲۳ پر اختلاف کے اردو اور عربی مفہوم پر گفتگو کچھ اس طرح کرتے ہیں:
’’وہ دراصل اردو کا اختلاف نہیں جو تضاد و تصادم کے معنی رکھتا ہے اور ایک دوسرے کا مدمقابل، حریف اور مخالف بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ عربی کا اختلاف ہے جس کے معنی تنوع، رنگارنگی اور گوناگونی اور بوقلمونی ہیں، یعنی وہ رنگارنگ سنتیں ہیں اور سب صحیح ہیں‘‘۔
یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دونوں زبانوں میں اختلاف کا لفظ دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ شاعر کہتا ہے:
اختلاف رنگ ہے اعجاز قدرت کی دلیل
پھول کھل کر کیوں نہ دعوائے خم عیسی کریں
تجزیاتی مطالعہ پر مبنی کچھ معروضات تھیں، جو اس مختصر سے مقالہ میں پیش کی گئیں۔ آخر میں اس بات کا ایک بار پھر اعتراف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ’’سنتوں کا تنوع‘‘ پروفیسر محمد یٰسین مظہر صدیقی صاحب کی ایک گراں قدر تصنیف ہے، یہ کتاب صحیح معنوں میں غوروفکر کی ایک وسیع دنیا کی سیر کرانے والی کتاب ہے۔ امید کہ اہل علم اس پر توجہ فرمائیں گے۔
حوالہ جات
(۱) امت کے اختلافات اور امت کو درپیش مسائل پر مولانا مودودی نے کافی کچھ قلم بند کیا ہے،اس سلسلے میں مولانا مودودی کے افکار کا تجزیاتی مطالعہ آج بھی غیرمعمولی اہمیت کا حامل ہوگا۔
(۲) ’’نماز اتحاد امت کی بنیاد‘‘، اس موضوع پر ڈاکٹر محی الدین غازی کا ایک بہت ہی وقیع اور فکر انگیز کتابچہ منشورات لاہور نے ۲۰۱۷ء میں شائع کیا تھا، یہ کتابچہ درحقیقت موصوف کی معرکہ آراء تصنیف ’’نماز کے اختلافات اور ان کا آسان حل‘‘ (شائع کردہ: ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرس، نئی دہلی۲۰۱۵ء) کی تلخیص ہے۔
(۳) رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۳۹۰
(۴) رسائل و مسائل حصہ اول، ص۱۶۴،۱۶۵
(۵) رسائل و مسائل ، حصہ اول، ص ۱۶۳
(۶) سنتوں کا تنوع، پروفیسر محمد یٰسین مظہر صدیقی، صفحہ ۸
(۷) یہ بات بھی محل نظر ہے کہ پوری کتاب میں سید مودودی علیہ الرحمہ کا تذکرہ ایک بار بھی نہیں کیا گیا، جبکہ سید مودودی کا موقف اس سلسلے میں زیادہ واضح اور دو ٹوک ہے۔
(۸) ایضا: ص ۸۔۹
(۹) ایضا: ص ۹
(۱۰) ایضا: ص ۹
(۱۱) ایضا: ص ۱۰
(۱۲) ایضا: ص ۳۱
(۱۳)ایضا: ص ۱۷۷
(۱۴) ایضا: ص ۱۸۱
(۱۵) ایضا: ص ۱۸۱
(۱۶) ایضا: ص ۱۸۱۔۱۸۲
(۱۷) ایضا:ص ۲۴
(۱۸)ایضا: ص ۳۹۔۴۰
(۱۹)ایضا: ص ۴۰
(۲۰) ایضا: ص ۴۰
(۲۱) ایضا: ص ۲۰
(۲۲) نماز کے اختلافات اور ان آسان حل، محی الدین غازی، ص ۳۲۔۳۳
(۲۳) ایضا، ص ۳۸
(۲۴)ایضا، ص ۳۵۔۳۶
(۲۵) مجاہد شبیر فلاحی نے سہ ماہی تحقیقات اسلامی ، علی گڑھ، ماہ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۸ء میں درج ذیل اہم امور کی طرف توجہ دلائی ہے:
(الف) صفحہ ۱۸، ۱۹ کی بحث میں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالۃ کے سلسلے میں خلط مبحث۔
(ب) صفحہ ۷۳ پر نماز کے اذکار کے سلسلہ میں کمزور رائے پر اعتماد۔
(ج) آنحضرتؐ کے حج کی تعداد کے سلسلہ میں موقف۔
(د) صفحہ ۱۱۴ پر قربانی کے گوشت کے سلسلہ میں مصنف کی گفتگو۔
(ہ) صفحہ ۱۱۶ پر سونے کی انگوٹھی کے استعمال سے متعلق گفتگو۔
(۲۶) سنن الترمذی، ت: شاکر :۲، ۸۲
(۲۷) فتح الباری لابن حجر :۲، ۳۱۵
(۲۸) صحیح البخاری:۲، ۱۳
(۲۹) صحیح البخاری: ۲، ۵۸
(۳۰) صحیح مسلم: ۱، ۵۰۴