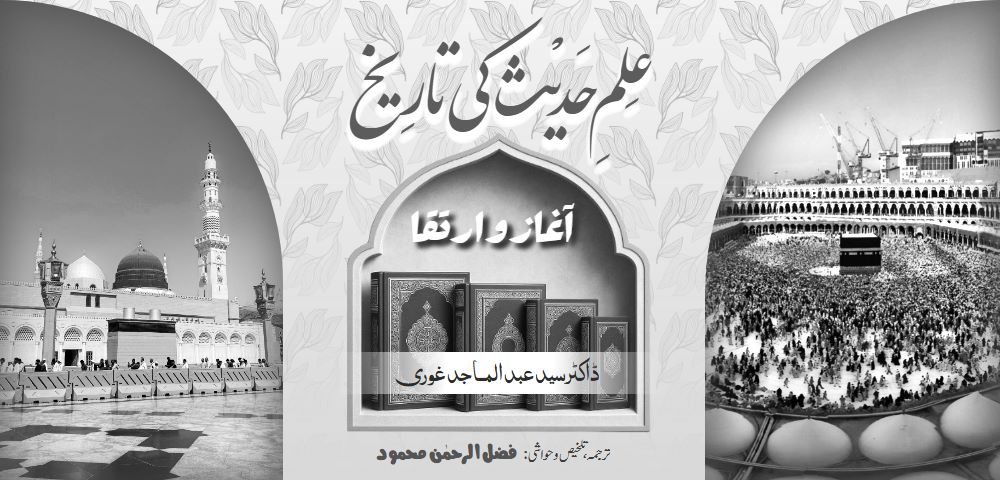طالب شریعت کے لیے علمِ حدیث کی اہمیت ڈھکی چھپی نہیں؛ کیوں کہ اسی علم کو وسیلہ بنا کر رسول اکرم ﷺ کی احادیث کو دسیسہ کاری، ردوبدل،دھوکے اور کذب بیانی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ علمِ حدیث کی پانچ شاخیں ہیں:
- اسناد
- تاریخ روات و علم رجال
- جرح و تعدیل کا بیان اورروات کے حالات کی جانچ پڑتال
- متن حدیث کا جائزہ اور اس سے متعلق علوم
- علم جرح وتعدیل 1۔
امام عراقی رحمہ اللہ2 اپنی ’’شرح الفیۃ ‘‘ میں اس علم کی اہمیت بیان کرتے ہوے فرماتے ہیں:
’’علمِ حدیث کی نہایت اہمیت ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے، اسی پر اکثر احکام کا مدار ہے، اسی سے حلال و حرام کی پہچان حاصل ہوتی ہے، علماے حدیث کی خاص اصطلاحات ہیں جنھیں سمجھنا طالب علم کے لیے ضروری ہے‘‘3۔
مولانا سید سلمان ندوی4 نے علمِ حدیث کی قدرومنزلت کے حوالے سے عمدہ کلام کیا ہے۔ روایت کی اہمیت بیان کرتے ہوے آپ فرماتے ہیں:
’’روایت ضروری چیز ہے۔ کسی بھی علم اور دنیوی معاملات میں نقل و روایت کے بغیر چارہ نہیں۔ انسان ہر واقعے میں حاضر نہیں رہ سکتا؛ اس لیے غیر حاضر لوگوں تک زبانی یا تحریری روایت سے ہی واقعات کو پہنچایا جاے گا۔ روایت ہی کے ذریعے سے پچھلی نسلوں کے واقعات بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچاے جا سکتے ہیں۔ گذشتہ اور موجودہ قوموں کی تاریخیں، مذاہب وادیان، حکما وفلاسفہ کے نظریات اور سائنس دانوں کی ایجادات و تجربات ہم تک نقل و روایت سے ہی پہنچی ہیں۔ احادیث چوں کہ خبریں ہیں؛ اس لیے ان کی جانچ پڑتال اور صحیح وسقیم کو الگ کرنے کے لیے ایسے اصول برتنا ضروری ہیں، جو ہم تمام روایات اور خبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دوسرے قواعد محدثین نے احادیث کی جانچ پڑتال کے لیے استعمال کیے ہیں۔ محدثین انھیں ’’اصول حدیث ‘‘ کا نام دیتے ہیں اور انھی کو برت کر صحیح اور ضعیف احادیث کو علاحدہ علاحدہ کیا ہے‘‘5۔
علمِ حدیث کن ادوار سے گزرا اور کیسے تکمیلی مرحلے میں داخل ہوا، یہ سب ذیل کی سطور میں بیان کیاگیا ہے۔
مترجم
علمِ حدیث کی تاریخ؛ آغاز و ارتقا
علم حدیث کی تاریخ کو تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
مرحلۂ اول: امام ابن صلاح سے قبل لکھی گئی کتب علمِ حدیث
مرحلۂ دوم: ابن صلاح کے مقدمے اور اس کے بعد لکھی گئی علمِ حدیث کی کتب
مرحلۂ سوم: کتب علمِ حدیث کا یہ تیسرا دور ہے۔ اس دور میں تالیف شدہ کتابوں میں جمود اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔
مرحلۂ اول: امام ابن صلاح سے قبل لکھی گئی کتب علمِ حدیث
چوتھی صدی ہجری میں’’ علم مصطلح الحدیث‘‘ یا ’’علم اصول حدیث ‘‘ یا ’’مصطلح الحدیث‘‘ ایک مستقل علم اختیار کر گیا۔ اسی زمانے میں علمِ حدیث میں کتابیں تصنیف کی گئیں اور مستقل رسالے لکھے گئے۔ جس سے اس علم کے مرتب اصول اور معروف قواعد سامنے آے۔
اصول حدیث کے بعض مسائل کی تسہیل اور بنیادی قواعد کی تدوین اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی، جب تاریخ رجال و کتب حدیث لکھنے کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل یہ علم سینوں میں محفوظ تھا اور زبانی بیان کیا جاتا تھا۔ جب کتب حدیث و رجال لکھی جانے لگیں تو ان میں ادھر ادھر سے اصول حدیث کے کچھ قواعد کا اضافہ بھی ہونے لگا؛ البتہ جامع اور خصوصی کتاب چوتھی صدی ہجری میں ہی سامنے آئی۔ اس سے قبل اگر کچھ لکھا گیا ہے تو وہ مستقل رسائل، بکھرے جملے یا علمِ حدیث کے بعض مسائل سے متعلق رسائل تھے۔
دوسری صدی ہجری کے آخری حصے میں علوم الحدیث کے بعض مباحث سے متعلق تالیف کا آغاز ہوا۔ موضوعات کی رعایت رکھتے ہوے مستقل ابواب کی شکل میں کتابیں لکھیں گئیں۔ ایک موضوع سے متعلق معلومات اکٹھی کر کے انھیں ایک جزو یا چند اجزا میں مکمل کیا جاتا، جس سے آج کے دور کے اعتبار سے مختصر کتاب وجود میں آجاتی۔ امام علی بن مدینی بصری (رحمہ اللہ )6 نے سب سے پہلے اس میدان میں قلم اٹھایا اور علوم الحدیث کی چند انواع سے متعلق کتابیں تحریر فرمائیں۔ ہر نوع پر علاحدہ کتاب لکھی۔ ان کی ’’علل‘‘ کے موضوع پر بھی ایک کتاب ہے۔
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب ’’ الرسالہ‘‘ میں علمِ حدیث و مصطلح کے بعض اہم مباحث و مسائل پر لکھا، مثال کے طور پر: قابل استدلال حدیث کی شرائط، ضبط راوی کی شرط، روایت بالمعنی، حدیث مدلس کی قبولیت۔ اسی طرح حدیث مرسل کے بارے میں ان کا موقف کافی مشہور ہے۔ مقدمۂ ابن صلاح پر حافظ عراقی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ انھوں نے حدیث حسن کو اپنی کتابوں میں برتا ہے7۔ ان کے بعد امام حمیدی نے بھی اصول روایت سے متعلق اپنی کتاب میں ان مباحث کا ذکر کیا ہے8۔
علوم الحدیث کا تکمیلی مرحلہ
تیسری صدی اور پانچویں صدی کے درمیانی زمانے میں علمِ حدیث کی تکمیل ہوئی۔ تیسری صدی ہجری میں یحیی بن معین9، احمد بن حنبل، امام بخاری، ابو جعفر مخرمی10 و دیگر حضرات نے بہ کثرت یا کمال تحقیق و تفتیش سے کام لیتے ہوے روات کو جرح و تعدیل کی میزان پر پرکھا۔ اسی طرح حافظ محمد بن عبد اللہ بن نمیر کوفی11 اور یعقوب بن شیبہ سدوسی بصری12 جیسے علماے حدیث نے احادیث کی جمع و تدوین کے دوران میں متن اور سند پر کلام کیا۔ تیسری صدی کے دوران میں ہی کتب رجال، کتب حدیث اور ایک موضوع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی مستقل میں کتابوں میں ذکر کیے گئے مسائل کے ذریعے اس علم کی شکل و صورت واضح طور پر سامنے آگئی تھی۔ اس کی مثال امام علی بن مدینی کی کتابیں ہیں۔ علمِ حدیث کے موضوعات پر لکھنے والے اس صدی میں بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر:
- امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی13 نے اپنی سنن کے عمدہ مقدمے میں علمِ حدیث پر کلام کیا ہے۔
- امام ابو عبد اللہ بخاری کی ’’الجامع الصحیح ‘‘ اور دیگر کتب ’’التاریخ ‘‘ و ’’الضعفاء‘‘ میں مسائل حدیث پر بہت جملے ملتے ہیں۔
- امام مسلم بن حجاج کی کتاب ’’الجامع الصحیح‘‘ کے آغاز میں ایک عمدہ مقدمہ ہے، جس میں انھوں نے علم مصطلح کے اچھے بھلے مسائل پر کلام کیا ہے۔ مصطلح کے قواعد پر تمہیدی کلام کے حوالے سے مقدمہ ٔ صحیح مسلم اور انھی کی کتاب ’’التمییز‘‘ کا شمار علمِ حدیث کی اولین کاوشوں میں ہوتاہے14۔
- امام ترمذی نے اپنی کتاب ’’الجامع ‘‘کے آخر میں ’’العلل الصغیر‘‘ کے نام سے نہایت بہترین جزو شامل کیا ہے۔ اس میں علمِ حدیث کے بہت سے اہم مباحث آگئے ہیں۔
- امام ابوداؤد سجستانی نے اہل مکہ کے نام اپنی ’’سنن‘‘ کی خصوصیات کے بارے میں ایک ’’رسالہ ‘‘ لکھا۔ اس میں بھی علمِ حدیث کے مسائل کی اچھی مقدار آگئی ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب ’’العلل و معرفۃ الرجال‘‘ میں علم مصطلح کے بارے میں بہت معلومات جمع کی ہیں۔
- امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ15 نے ’’التسویۃ: بین حدثنا واخبرنا ‘‘ کے نام سے ایک مختصر اور عمدہ رسالہ لکھا ہے، جس میں انھوں نے ثابت کیا ہے کہ، خواہ آپ شیخ کی زبانی احادیث سنیں یا ان کے سامنے پڑھیں، دونوں حالتوں میں ’’حدثنا ‘‘ اور ’’اخبرنا‘‘ کے الفاظ بغیر کسی فرق کے استعمال کر سکتے ہیں۔
- امام ابن عبد البر اندلسی16 نے بھی ’’التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید‘‘ کے وسیع و کامل مقدمے میں علمِ حدیث پر کلام کیا ہے۔
- امام ابن اثیر17نے بھی اپنی کتاب ’’جامع الاصول فی احادیث الرسول ‘‘ کے مقدمے میں علم مصطلح پر قلم اٹھایا ہے۔ اصول حدیث اور اس کے احکام و متعلقات پر یہ مباحث انھوں نے تیسرے باب میں لکھے ہیں۔
علوم الحدیث کے مباحث کی جمع و تدوین
چوتھی صدی ہجری میں چند علماے حدیث نے علمِ حدیث کے بکھرے قواعد و مباحث کو ایک جامع کتاب میں جمع کرنا شروع کیا۔ چناں چہ پہلے سے لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے انھوں نے ایک فن کی متفرق معلومات کو یک جا کر دیا، جو باتیں پہلوں سے رہ گئی تھیں ان کا اضافہ کیا، پرانے علما کی طرح مکمل سند کے ساتھ معلومات ذکر کر کے ان پر تبصرے (و حواشی) تحریر کیے اور مسائل کا استنباط کیا، جس کی وجہ سے علوم حدیث میں ایسی کتابیں منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوئیں، جن سے استفادہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ اہم کتابوں کے نام درج ذیل ہیں:
المحدث الفاصل بین الراوی والواعی: یہ قاضی ابو محمد الحسن بن خلاد فارسی رامہرمزی18 کی کتاب ہے۔ تدوین علمِ حدیث کی فہرست میں یہ پہلی جامع و مستقل کتاب شمار ہوتی ہے۔
معرفۃ علوم الحدیث وکمیۃ اجناسہ: یہ امام ابو عبد اللہ الحاکم نیشاپوری19 کی کتاب ہے۔ امام ابن خلدون فرماتے ہیں: علوم الحدیث کے جلیل القدر علما وائمہ میں ابو عبد اللہ الحاکم کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی تالیفات مشہور ہیں۔ انھوں نے ہی علمِ حدیث کو حسن ترتیب دی اور اس کی بھلائیوں کو اجاگر کیا20۔
الکفایۃ فی معرفۃ اصول الروایۃ: یہ محدث ابوبکر خطیب بغدادی21 کی کتاب ہے۔
الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع: یہ کتاب بھی خطیب بغدادی نے لکھی ہے۔ طلب حدیث اور راوی کے اخلاق وآداب کے موضوع پر اس کتاب کا شمار اولین کاوشوں میں ہوتا ہے۔
الالماع فی اصول الروایۃ والسماع: یہ قاضی و حافظ عیاض بن موسی یحصبی22 کی تالیف ہے۔ اس کے عنوان سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں حصول حدیث کے مختلف طریقوں اور روایت حدیث کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ بہت مفید کتاب ہے۔
مالایسع المحدث جہلہ: یہ ابوحفص عمر بن عبد المجید میانجی23 کا تقریبا سات صفحات پر مشتمل مختصر رسالہ ہے24۔
مرحلۂ دوم: ابن صلاح کا مقدمہ اور اس کے بعد لکھی گئی کتب علمِ حدیث
یہ مرحلہ ساتویں صدی سے شروع ہو کر دسویں صدی تک جاتا ہے۔ اس مرحلے میں علمِ حدیث کی تدوین بام عروج تک پہنچ گئی۔ ایسی تصانیف و تالیفات سامنے آئیں، جن میں علمِ حدیث کی انواع کا مکمل احاطہ کیا گیا، عبارتوں کی اصلاح کی گئی اور مسائل باریکی سے لکھے گئے۔ ان تصانیف و تالیفات کو لکھنے والے گذشتہ بڑے ائمہ کی طرح علمی رسوخ کے حامل تھے، انھوں نے احادیث مکمل یاد کیں، فنون حدیث اور اسانید و متون میں علم و درایت کے لحاظ سے مہارت پیدا کی۔
علمِ حدیث کی تدوین میں اس گراں قدر تبدیلی کے پیش رو ’’امام ابوعمرو عثمان بن عبد الرحمن شہرزوری‘‘ ہیں۔ آپ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہیں25۔ ’’معرفۃ علوم انواع علوم الحدیث‘‘ کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جو مقدمۂ ابن صلاح کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ یہ کتاب متاخرین علما کا سہارا ہے۔ ابن صلاح نے یہ کتاب وقفے وقفے سے املا کرائی، اسی وجہ سے اس کتاب میں مناسب علمی ترتیب نظر نہیں آتی۔ پینسٹھ انواع پر مشتمل اس کتاب میں آپ نےخطیب بغدادی ودیگر علما کی اصول فقہ و اصول حدیث پر لکھی گئی کتابوں سے متفرق مواد اکٹھا کر دیا ہے۔ مواد کی کثرت اور حسن تحریر کی بنا پر یہ کتاب مشہور ہو گئی۔ علما اس کی تدریس، تشریح، تلخیص، تائید و اختلاف اور اس کے مشمولات کو نظمانے میں مصروف ہوگئے۔ یہاں تک کہ اصول کی ہر بنیادی کتاب، جیسے سخاوی کی فتح المغیث اور سیوطی کی تدریب الراوی وغیرہ، مقدمہ ٔ ابن صلاح کی چراگاہ سے مستفید اور اسی کی خوشہ چین ہے۔
امام ابن صلاح نے بڑھتی عمر میں یہ کتاب لکھی۔ اس وقت آپ کا علم کامل اور ٹھوس ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیف میں ٹھہراؤ اور گہرے تدبر سے کام لیا۔ بہت سی مجالس میں اسے املا کرا کے مکمل کیا۔ ان مجالس کے درمیان وقفے بھی آتے رہے۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، جس میں اس فن کی خصوصیت اور شدید ضرورت کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
’’تحقیق کار کو جب اس فن کی مشکلات کا گرہ کشا نہ ملا اور اس علم کے متعلق سوال کرنے والے کو فن کا شناسا نہ مل سکا تو خداوند کریم نے مجھ پر احسان کرتے ہوے ’’معرفۃ انواع علم الحدیث‘‘ کتاب لکھنے کی توفیق بخشی۔ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کتاب نے فن حدیث کے پوشیدہ را ز اور ادبی مشکلات آشکارا کر دیے ہیں‘‘۔
اس کے بعد ابن صلاح نے علوم حدیث کی پینسٹھ انواع ذکر کر کے مضامین کتاب کی ایک فہرست مہیا کی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انواع کسی خاص نظم و ترتیب کے بغیر ذکر کر دی گئی ہیں۔ اسناد سے متعلق ایک نوع ذکر کرنے کے بعد متن یا اسناد و متن دونوں سے متعلق نوع کا ذکر کر دیتے ہیں۔
مصطلح کے میدان میں اپنی بہت زیادہ خوبیوں کے باعث یہ کتاب ہر صاحب حدیث، محدث اور عالم کے لیے رہ نما اور چشمۂ شیریں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس کے ظہور پذیر ہونے کے بعد علما نے اس پر شرحیں لکھیں، اس کا اختصار کیا، حواشی سے مزین کیا اور اس کے مضامین کو نظمایا۔ جس کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے:
مقدمۂ ابن صلاح کی شرحیں
الجواہر الصحاح فی شرح علوم الحدیث لابن الصلاح: یہ عزالدین ابو عمرو عبد العزیز بن محمد بن جماعہ دمشقی26 کی کتاب ہے۔
الشذا الفیاح من علوم الحدیث: یہ برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن موسی بن ایوب ابناسی قاہری27 کی کتاب ہے۔
محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح: یہ شیخ الاسلام سراج الدین ابو حفص عمر بن رسلان بن نصیر مصری بلقینی28 کی کتاب ہے۔
مقدمۂ ابن صلاح پر ’’النکت‘‘ کے عنوان سے لکھی گئی کتب
النکت علی کتاب بن الصلاح: یہ امام بدر الدین زرکشی ابو عبد اللہ محمد بن بہادر مصری29 کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جامعیت ہے۔ یہ قسم ہا قسم کے مضامین کا گل دستہ ہے۔ اس میں حدیث، فقہ، اصول، لغت و نحو کے مباحث کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ امام زرکشی جری ناقد تھے۔ اسی لیے انھوں نے ابن صلاح پر استدراکات لکھے اور بعض دیگر اقوال کو بھی ہدف تنقید بنایا۔
التقیید والایضاح لما اطلق واغلق من کتاب ابن الصلاح: یہ حافظ زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین عراقی کی کتا ب ہے۔ اس کتاب میں مولف نے ابن صلاح کی تمام عبارتیں ذکر نہیں کیں؛ بلکہ صرف انھی عبارتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں مولف کا گمان تھا کہ صرف ان کی تشریح اور انھی پر نکتہ آفرینی کی ضرورت ہے۔
اصلاح ابن الصلاح: یہ حافظ علاء الدین ابو عبد اللہ مغلطائی بن قلیج بکری مصری کی کتاب ہے۔
النکت علی کتاب ابن الصلاح: یہ حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی مصری30 کی کتاب ہے۔
مقدمۂ ابن صلاح کے مختصرات
ارشاد طلاب الحقائق الی معرفۃ سنن خیرالخلائق: یہ ابو زکریا یحیی بن شرف الدین النووی31 کی کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھنے کے بعد امام نووی نے ’’تقریب‘‘ کے نام سے اس کا خلاصہ لکھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسی ’’تقریب‘‘ کی تدریب الراوی میں تشریح کی ہے۔
رسوم التحدیث فی علوم الحدیث: یہ امام ابراہیم بن عمر بن ابراہیم جعبری32 کی عمدہ و مختصر کتاب ہے۔ طویل شرح و توضیح میں جاے بغیر ایک عالم اس کتاب کے ذریعے علمِ حدیث کے مباحث یاد رکھ سکتا ہے۔
المنہل الروی فی علوم الحدیث: یہ قاضی بدر الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ حموی33 کی تصنیف ہے۔ یہ مقدمۂ ابن صلاح کا عمدہ خلاصہ ہے۔
الخلاصۃ فی معرفۃ الحدیث: یہ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی مصری شافعی34 کی تالیف ہے۔ علمِ حدیث میں یہ مختصر رسالہ ہے۔ اس رسالہ میں مولف نے حدیث کی اہم مصطلحات کا تعارف کرایا ہے۔
المنتخب فی علوم الحدیث: یہ قاضی ابو الحسن علی بن عثمان ماردینی مصری حنفی کی تالیف ہے۔ آپ ’’ابن ترکمانی‘‘35 کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن فہد اپنی کتاب ’’لحظ الالحاظ‘‘36 میں فرماتے ہیں: ’’یہ ابن صلاح کی کتاب کا بہترین و کامل اختصار ہے‘‘۔
اختصار علوم الحدیث: یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی37 کی کتاب ہے۔ علامہ احمد شاکر نے ’’الباعث الحثیث ‘‘ کے نام سے اس کی شرح اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس پر ’’تعلیقات‘‘ لکھیں۔
المقنع فی علوم الحدیث: یہ حافظ سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد انصاری مصری کی کتاب ہے۔ آپ ’’ابن الملقن‘‘38 کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کا شمار مقدمۂ ابن صلاح کے بہترین خلاصوں میں ہوتا ہے۔ مولف نے اس کتاب میں مقدمہ ٔ ابن صلاح میں کی گئی انواع کی تقسیم ہی کی پیروی کی ہے اور ایک ماہر عالم کی مانند علم اصطلاح کا احاطہ کیا ہے۔
مقدمۂ ابن صلاح کے منظومات
مقدمۂ ابن صلاح پر لکھے گئے اہم منظومات یہ ہیں:
التبصرۃ والتذکرۃ: یہ امام زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین عراقی کا منظومہ ہے۔ اس کی شرح انھی کے شاگرد حافظ سخاوی نے ’’فتح المغیث‘‘ کے نام سے لکھی۔
الفیۃ السیوطی فی علم الحدیث: یہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی کا منظومہ ہے۔ آپ نے اس منظومے کی خود ہی ’’البحر الذی زخر فی شرح الفیۃ الاثر‘‘ کے نام سے شرح لکھی؛ لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر انیس طاہر انڈونیشی نے اس کتاب کو ایڈٹ کرکے ’’مکتبۃ الغرباءالاثریہ‘‘ سے چھپوایا۔
محاسن الاصطلاح و تضمین کتاب ابن الصلاح: یہ امام بلقینی کی کتاب ہے۔ اسے محدث زین الدین ابو العز طاہر بن حسن حلبی حنفی نے نظمایا ہے۔ آپ بلقینی کے شاگرد اور ’’ابن حبیب‘‘39 کے نام سے مشہور ہیں۔ حافظ ابن حجر اپنی کتاب ’’انباءالغمر ‘‘ میں فرماتے ہیں: ’’یہ بلقینی کی کتاب محاسن الاصطلاح کا سب سے اچھا منظومہ ہے‘‘40۔
اس طرح بعد میں آنے والے ہر عالم نے ابن صلاح کی کتاب پر بھروسا کیا۔ کسی نے اس کا خلاصہ لکھا، کسی نے نظمایا اور کچھ حضرات نے اس کی شرحیں لکھیں اور حواشی سے مزین کیا۔
امام ابن صلاح کے بعد علم مصطلح میں لکھی گئی مستقل کتب
ایک زمانہ ایسا آیا جس میں علما نے مستقل کتب کی تالیف کا آغاز کیا۔ یہ علما علمی قواعد کی وضاحت میں ابن صلاح کے محض پیرو نہیں تھے؛ بلکہ انھوں نے اپنی ذاتی آرا پیش کیں، اکثر مقامات پر ان کے مقرر کردہ قواعد مباحثے کی کسوٹی پر پرکھے یا ان سے مخالفت کی۔ یہاں میں علم مصطلح الحدیث کے موضوع پر لکھی گئی ان کی چند تالیفات کا ذکر کرتا ہوں۔ ان تالیفات میں تقلید سے زیادہ اختراع و اجتہاد کی شان نظر آتی ہے:
الاقتراح فی بیان الاصطلاح: یہ امام ابن دقیق العید41 کی تصنیف ہے۔
الموقظۃ فی علم مصطلح الحدیث: یہ امام محمد بن احمد ذہبی42 کی تصنیف ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں روشن فوائد اور یکتا جواہر پارے موجود ہیں۔ ’’الموقظۃ‘‘ امام ابن دقیق العید کی کتاب ’’الاقتراح‘‘ کا خلاصہ ہے۔
مختصر فی علوم الحدیث: یہ سید شریف جرجانی43 کی کتاب ہے۔
نخبۃ الفکر و شرحہ نزہۃ النظر: یہ امام ابن حجر عسقلانی کی تالیف ہے۔
فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث: یہ امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی44 کی تصنیف ہے۔ کشف الظنون کے مولف فرماتے ہیں: ’’الفیۃ العراقی کی شروحات میں شاید یہ سب سے اچھی شرح ہے‘‘45۔
تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: یہ امام حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی46 کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صرف معلومات جمع کر دی گئی ہیں؛ لیکن علمِ حدیث کے مسائل پر کچھ اچھے مباحثے بھی موجود ہیں۔
مرحلۂ سوم: علمی جمود اور ٹھہراؤ کا دور
علمِ حدیث کا یہ تیسرا دور دسویں صدی سے لے کر پندرھویں صدی ہجری کے آغاز تک جاتا ہے۔ اس مرحلے میں علمی اجتہاد کا عنصر غائب ہوگیا، تصنیف میں جدت باقی نہ رہی، علوم حدیث کے میدان میں شعری و نثری مجموعے کثرت سے سامنے آنے لگے، لکھاری، مولفین کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر لفظی موشگافیوں میں مصروف ہوگئے، مضمون کی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا اور تحقیق یا اجتہاد دروازہ بند ہو گیا۔
اس زمانے میں سامنے آنے والی چند تالیفات کے نام درج ذیل ہیں:
منظومۂ بیقونیہ: یہ عمر بن محمد بن فتوح بیقونی47 کی تالیف ہے۔
توضیح الافکار فی شرح تنقیح الانظار: یہ امام محمد بن اسماعیل امیر صنعانی48 کی تصنیف ہے۔
شرح شرح نخبۃ الفکر فی مصطلحات اہل الاثر: یہ محدث علامہ علی بن سلطان محمد القاری49 کی تالیف ہے۔ نخبۃ الفکر کی یہ سب سے اچھی اور عمدہ شرح ہے۔
مصطلح کے موضوع پر دورِ جدید میں لکھی جانے والی کتب
دور جدید میں علمِ حدیث کے میدان میں کئی کاوشیں منصۂ علم پر جلوہ گر ہوئی ہیں۔ ان کے لکھنےوالے جلیل القدر علما تھے۔ ان کاوشوں میں دور جدید کی زبان، منہج و اسلوب کو اختیار کر کے پرانے علما کے بیان کیے ہوے مباحث کو آسان انداز میں ڈھالا گیا ہے۔تحریک نو کے اس مرحلے میں اصول حدیث و مصطلح کے موضوع پر لکھی گئی چند اہم کتابوں کے نام یہ ہیں:
قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: یہ شیخ جمال الدین قاسمی50 کی کتاب ہے۔
توجیہ النظر الی اصول اہل الاثر: یہ علامہ طاہر جزائری51 کی تالیف ہے۔
الوسیط فی علوم الحدیث: یہ علامہ محمد بن محمد ابوشہبہ52 کی کتاب ہے۔ دور جدید میں لکھی جانے کتب حدیث میں یہ سب سے عمدہ کتاب ہے۔
تیسیر مصطلح الحدیث: یہ استاد محمود طحان53 کی تصنیف ہے۔ علوم الحدیث کی یہ سب سے آسان اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں فاضل مولف نے مبتدی طالب علموں کی رعایت کرتے ہوے مباحث ذکر کیے ہیں۔
تحریر علوم الحدیث: یہ شیخ عبد اللہ بن یوسف جدیع54 کی کتاب ہے۔ اس میں مولف نے متقدمین اور سلف صالحین کے انداز کو اپنایا ہے۔
منہج النقد فی علوم الحدیث: یہ شیخ نور الدین عتر55 کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں دیگر کتابوں کی بہ نسبت مضامین کی بڑے اچھے طریقے سے تفصیل بیان کی گئی ہے اور مباحث کی تقسیم عمدہ ہے۔
معجم المصطلحات الحدیثیہ: یہ شیخ نور الدین عتر کی کتاب ہے۔ مصطلح کے موضوع پر یہ پہلی قاموس ہے، جو بعد میں اسی طرز پر لکھی جانے والی قوامیس کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔
حواشی
1 . لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث، عبد الفتاح أبو غدة، ن: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط الأولى : 1414هـ : 1984م (صـ: 101)
2۔ ان کا نام : زین الدین عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن عراقی ہے، اپنے زمانے کے حافظ حدیث تھے۔ قاہرہ میں جمادی الاولی کے مہینے میں 725ہجری میں ولادت ہوئی۔ فن حدیث حاصل کر کے اس میں مہارت پیدا کی اور ہم عصروں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ کے اساتذہ بھی آپ کی فنی مہارت کی بڑھ چڑھ کر تعریف کرتے۔ آپ کی کئی تالیفات ہیں: الفیہ اور اس کی شرح، نظم الاقتراح، تخریج احادیث الاحیا، تکملہ شرح الترمذی لابن سید الناس۔ آپ نیک اور متواضع تھے۔ ہاتھ تنگ تھا۔ 806ہجری میں وفات ہوئی۔ (حسن المحاضرۃ فی تاریخ مصر والقاہرہ، سیوطی: 1/360)
3۔ شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، تحقيق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل، ن : دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى: 1423هـ : 2002م، (1/97)
4۔ آپ کانام سلمان بن طاہر الحسینی ندوی ہے۔ ایک داعی اور مربی کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لکھنؤ میں ۱۹۵۴ ء میں آپ کی پیدایش ہوئی۔ ندوۃ العلما، لکھنو، انڈیا سے حدیث ڈیپارٹمنٹ سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ امام محمد بن سعود یونی ورسٹی (ریاض) میں کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ عربی واردو میں آپ کی کئی کتابیں ہیں،مثال کے طور پر: جمع ألفاظ الجرح والتعديل ودراستها من كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، التعريف الوجيز بكتب الحديث، لمحة عن علم الجرح والتعديل، الأمانة في ضوء القرآن (دیکھیے: المدخل إلى دراسة جامع الترمذي مع تقديم وتعليق الشيخ سلمان الحسيني الندوي: صـ22)
5۔ تحقيق معنى السنة ومكانتها، مقالہ: سید سلمان ندوی، مجلہ (المسلمون)، جلد : ۶،ص: ۵۶۵، شمارہ : ۶ (ص: ۴۹)
6۔ ان کانام ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن جعفر ہے۔ اپنے زمانے کے حافظ حدیث تھے۔ اعیان حدیث اور ثقہ راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علل الحدیث میں اعلی اور آخری درجے پر فائز تھے۔ امام بخاری کے استاد اور یحیی بن سعید القطان کے شاگرد ہیں۔ کہا جاتا ہےکہ ان کی دو سو(۲۰۰) تصانیف ہیں۔ سامرا میں ذی القعدہ ۲۳۴ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ (دیکھیے: میزان الاعتدال، ذہبی: ۳/۱۳۸)
7۔ ص: ۸ و ۳۸
8۔ المنهج المقترح لفهم المصطلح، الشريف حاتم العوني بن عارف العوني، ن: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 1416هـ : 1996م، (صـ183)
9۔ ان کا نام یحیی بن معین بن عون بن زیاد ہے۔ ابو زکریا کنیت ہے۔ تاریخ روات کے ماہرین اور ائمۂ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علم رجا ل میں ان کی کتاب التاریخ والرجال، معرفۃ الرجال اور الکنی والاسماء ہے۔ ان کے والد بہت سا مال چھوڑا تھا، جسے انھوں نے طلب حدیث میں خرچ کر دیا۔ بغداد میں زندگی گزاری۔ ۲۳۳هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: الاعلام للزرکلی: ۸/۱۷۳)
10۔ ان کانام محمد بن عبد اللہ بن مبارک، ابوجعفر مخرمی ہے۔ حافظ حدیث اور ثقہ راوی ہیں۔ حلوان کے قاضی تھے۔ امام یحیی بن معین اور یحیی بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں۔ ۲۵۴هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: تہذیب الکمال، مزی: ۲۵/۵۳۸)
11۔ ان کا نام محمد بن عبد اللہ بن نمیر، ابو عبد الرحمن ہمدانی کوفی ہے۔ حافظ، حجت اور شیخ الاسلام کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کے ہم عصر ہیں۔ امام بخاری و مسلم نے ان کی روایات اپنی ’’صحیحین ‘‘ میں ذکر کی ہیں۔ علم، فہم، سنت و زہد سے متصف تھے۔ ۲۳۴هـ کو شعبان یا رمضان میں ان کی وفات ہوئی۔ (دیکھیے: سیر اعلام النبلاء، ذہبی: ۱۱/۴۵۷)
12۔ ان کا نام یعقوب بن شیبہ بن صلت بن عصفور ہے۔ اپنے زمانے کے حافظ و علامہ تھے۔ ابو یوسف کنیت تھی۔بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ المسند الکبیر المعلل کے نام سے کتاب لکھی۔ اس سے بہترین کوئی اور مسند نہیں لکھی گئی لیکن امام انھیں مکمل نہ کر سکے۔ بڑے علماے حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خطیب بغدادی و دیگر نے ان کی توثیق کی ہے۔ عراق کے قاضی رہے۔ ۲۶۲هـ میں ان کی وفات ہوئی (دیکھیے: تذکرۃ الحفاظ، ذہبی: ۲/۱۱۸)
13۔ ان کا نام عبد اللہ بن عبد الرحمن بن فضل بن بہرام بن عبد الصمد ہے۔ کنیت ابو محمد الدارمی ہے۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت اسفار کیے۔ ثقاہت، سچائی، ورع و زہد کے مالک تھے۔ حدیث پاک کو نہایت مضبوطی سے حفظ و جمع کیا۔ حدیث میں ’’مسند‘‘ لکھی اور تفسیر میں طبع آزمائی کی۔ ۲۵۰هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: تاریخ بغداد: ۱۱ /۲۰۹)
14۔ مقالات الكوثري، محمد زاهد الكوثري، ن: المكتبة الوقفية، القاهرة، (صـ: 83) تاریخ طباعت و اشاعت مذکور نہیں۔
15۔ ان کا نام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ ازدی حنفی ہے۔ ۲۳۷هـ میں ولادت ہوئی۔ ثقہ، ثبت، فقیہ و عقل مند تھے۔ امام مزنی کے بھانجے تھے۔ اختلاف العلماء، شروط، احکام القرآن العظیم اور معانی الآثار کے نام سے کتابیں لکھیں۔ ۸۰ سال سے زیادہ کی عمر پا کر ۳۲۱هـ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ (دیکھیے: تذکرۃ الحفاظ، ذہبی: ۳/۲۱)
16۔ ان کا نام ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم نمری ہے۔ فقیہ و حافظ اور بلند و بالا تصانیف کے حامل ہیں۔ علم حدیث، رجال، قراءات و نسب وغیرہ کے ماہر۔ امام مالک کی موطا پر ’’التمہید‘‘ اور ’’الاستذکار ‘‘ کے نام سے کتابیں لکھیں۔ صحابہ کے حالات پر الاستیعاب نامی کتاب لکھی۔ ان کے علاوہ دیگر تصانیف بھی ہیں۔ ۴۶۳هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: سیر اعلام النبلاء، ذہبی: ۱۸/۱۵۳)
17۔ ان کا نام مبارک بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الکریم شیبانی جزری ہے۔ کنیت ابو السعادات ہے۔ آپ محدث اور ماہر لغت تھے۔ جزیرہ ٔ ابن عمر میں پیدا ہوے اور وہیں پلے بڑھے۔ اس کے بعد موصل چلے آئے۔ آخری عمر میں بیمار ہوگئے اور ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ موت تک یہ بیماری رہی یہاں تک کہ موصل کے ایک گاؤں میں فرشتۂ اجل کو لبیک کہا۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی تمام کتابیں بیماری کی حالت میں لکھیں۔ اپنے طلبہ کو املا کرا دیتے۔ ان کی کتابوں میں النہایہ فی غریب الحدیث، جامع الاصول فی احادیث الرسول، الانصاف فی الجمع بین الکشف والکشاف، المرصع فی الآباء والامہات والبنات، الشافی فی شرح مسند الشافعی، المختار فی مناقب الاخبار، تجرید اسماء الصحابہ، منال الطالب فی شرح طوال الغرائب، شامل ہیں۔ ۶۳۰هـ میں ان وفات ہوئی۔ (الاعلام، زرکلی: ۴/۳۳۱)
18۔ ان کا نام حسن بن عبد الرحمن خلاد رامہرمزی فارسی اور ابو محمد کنیت ہے۔ قاضی، ادیب اور اپنے زمانے کے محدث عجم تھے۔ امام ذہبی ان کی کتاب ’’المحدث الفاصل ‘‘ کے بارے میں فرماتے ہیں: ’’کیا ہی خوب کتاب ہے‘‘۔ شاعر تھے۔ ان کی کتابوں میں ربیع المتیم، الامثال، نوادر، الرثاء والتعازی اور ادب الناطق شامل ہیں۔ (دیکھیے: الاعلام، زرکلی: ۲/۱۹۴)
19۔ ان کا نام محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمدویہ، ابو عبد اللہ الحاکم ہے۔ امام، حافظ، ناقد، علامہ اور شیخ المحدثین۔ تصنیف و تخریج، جرح و تعدیل اور تصحیح و تعلیل میں ماہر اور علم کے سمندر تھے۔ مزاج میں ہلکا سا تشیع تھا۔ ان کی کتابوں میں معرفۃ علوم الحدیث، مستدرک الصحیحین، تاریخ النیسابوریین، مزکی الاخبار، المدخل الی علم الصحیح، الاکلیل اور فضائل الشافعی وغیرہ شامل ہیں۔ ۴۰۵هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: سیر اعلام النبلاء، ذہبی: ۱۷/۱۶۲)
20۔ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبوزيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة، ن: دار الفكر، بيروت، ط الثانية: 1408هـ : 1988م، (صـ: 559)
21۔ ان کا نام ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی بغدادی ہے۔ اپنے زمانے سب سے بڑے حافظ حدیث، ہم عصروں پر فائق، صاحب تصانیف، خاتمہ ٔ حفاظ، جمع و تصنیف، تصحیح و تعلیل، جرح وتعدیل اور تاریخ میں ماہر۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتے۔ پچاس سے زیادہ کتابیں لکھیں، ان میں : التاریخ، شرف اصحاب الحدیث، الکفایۃ فی علم الروایۃ اور الفقیہ والمتفقہ شامل ہیں۔ ۴۶۳هـ وفات ہوئی۔ (دیکھیے : سیر اعلام النبلاء، ذہبی: ۱۸/۲۷۰)
22۔ ان کا نام عیاض بن موسی بن عیاض یحصبی اور کنیت ابو الفضل بستی ہے۔ ان کی تصانیف مفید ہیں۔ قاضی عیاض کا علم پھیلا اور نام مشہور ہوا۔ ان کی کتابوں میں الشفاء فی شرف المصطفی، ترتیب المدارک وتقریب المسالک، العقیدہ، شرح حدیث ام زرع، جامع التاریخ اور مشارق الانوار شامل ہیں۔ ۵۴۴هـ وفات ہوئی۔ (دیکھیے: تاریخ الاسلام، ذہبی: ۱۱/۸۶۰)
23۔ ان کا نام عمر بن عبد المجید بن عمر بن حسین، ابو حفص قرشی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جمادی الاولی کے مہینے سنہ ۵۸۱هـ میں وفات ہوئی۔ مضبوط محدث اور نیک انسان تھے۔ (دیکھیے: تاریخ الاسلام، ذہبی: ۱۲/۷۳۶)
24۔ منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين محمد عتر الحلبي، ن: دار الفكر، دمشق – سورية، ط الثالثة: 1418هـ : 1997م، (صـ: 64)
25۔ ان کا نام تقی الدین، ابو عمرو عثمان بن مفتی صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان بن موسی کر دی، شہرزوری ہے۔ اپنے والد سے فہم دین حاصل کیا۔ دمشق میں مدرسہ ٔ اشرفیہ کے شیخ الحدیث رہے۶۴۳هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: سیر اعلام النبلاء، ذہبی: ۲۳/۱۴۰)
26۔ ان کا نام عزالدین عبد العزیز بن محمد بن جماعہ الکنانی ہے۔ ابوحیان سے علم نحو حاصل کیا۔ مصر کے لمبے عرصے تک قاضی رہے۔ حرمین میں آخری گزارنے خواہش تھی، لہذا قضا کے عہدے سے استعفا دیا۔ اس کے بعد حج کیا اور مکہ مکرمہ کے قبرستان ’’معلی ‘‘ میں فضیل بن عیاض ابو القاسم قشیری کے پہلو میں دفن ہوے۔ ۷۶۶هـ میں فوت ہوے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھیں، ان میں ’’مناسک الحج علی المذاہب الاربعہ ‘‘ بھی شامل ہے۔ آپ بھلے اور نیک انسان تھے۔ (دیکھیے: العقد المذہب فی حملۃ المذہب لابن الملقن، ص: ۴۱۱، وجلاءالعینین فی محماکمۃ الاحمدین للعلامہ آلوسی، ص: ۳۹)
27۔ ان کانام ابراہیم بن موسی بن ایوب شیخ برہان الدین اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ قاہرہ میں شافعیہ کے بڑے رہ نماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فقہ و اصول اور عربی زبان میں مہارت تھی۔ تدریس بہت زیادہ کی، فتوی اور تصنیف کا کام کیا۔ محرم کے مہینے میں حج سے واپس ہوتے ہوے ۸۰۲هـ میں وفات پائی۔ ( دیکھیے: ذیل التقیید فی رواۃ السنن والمسانید، ابو طیب مکی: ۱/۴۵۶)
28۔ آپ کا نام سراج الدین ابو حفص عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح کنانی ہے۔ اپنے زمانے کے مجتہد اور آٹھویں صدی کے عالم تھے۔ فقہ، حدیث و اصول میں مہارت پیدا کی۔ افتا اور مختلف مذاہب کے علم میں حرف آخر تھے۔ اجتہاد کا رتبہ حاصل تھا۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں ان کی تصانیف بھی ہیں، ان میں حواشی الروضہ، شرح بخاری، شرح ترمذی، حواشی الکشاف شامل ہیں۔ بہاءبن عقیل فرماتے ہیں: اپنے زمانے میں فتوی دینے کے سب سے زیادہ حق دار تھے۔ ۱۰ دی قعدہ ۸۰۵هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، سیوطی: ۱/۳۲۹)
29۔ ان کا مکمل نام بدرالدین محمد بن عبد اللہ بن بہادر زرکشی ہے۔ آپ ۷۴۵هـ کو پیدا ہوے۔ اسنوی، ابن کثیر، اذرعی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ کئی فنون میں تصانیف چھوڑیں۔ ان میں چند کے نام یہ ہیں: الخادم علی الرافعی والروضہ، شرح المنہاج، الدیباج، شرح جمع الجوامع، شرح البخاری، التنقیح علی البخاری، شرح التنبیہ، البرہان فی علوم القرآن، القواعد فی الفقہ، احکام المساجد، تخریج احادیث الرافعی، تفسیر القرآن۔ یہ کتاب آپ سورت مریم تک ہی لکھ پاے۔ البحر فی الاصول، سلاسل الذہب فی الاصول والنکت علی ابن الصلاح۔ ان کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں۔ ۳ رجب، بروز اتوار، ۷۹۴هـ میں وفات ہوئی۔ (حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، سیوطی: ۱/۴۳۷)
30۔ ان کا مکمل نام : ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی عسقلانی ہے۔ ۷۷۳هـ میں ولادت ہوئی۔ ابتدا میں ادب و علم شعر کی طرف توجہ کی اور درجۂ کمال کو پہنچے اس کے بعد حدیث کی طرف توجہ کی۔ حافظ ابو الفضل زین الدین عراقی کی شاگردی اختیار کی۔ علم حدیث کے تمام فنون میں گوے سبقت لے گئے۔ حدیث کے میدان میں تمام دنیا میں حرف آخر تھے۔ ان کے زمانے میں کوئی اور حافظ حدیث نہ تھا۔ بہت سی کتابیں لکھیں، مثال کے طور پر: شرح بخاری، تعلیق التعلیق، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب وغیرہ۔ ۸۵۲هـ وفات ہوئی۔ (دیکھیے: حسن المحاضرۃفی تاریخ مصر والقاہرۃ، سیوطی: ۱/۳۶۳)
31۔ ان کام نام: یحیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام بن محمد بن جمعہ نووی ہے۔ ابوزکریا کنیت ہے۔ شافعی مسلک کے مدون تھے۔ الروضہ، مجموع اور المنہاج کے نام سے کتابیں لکھیں۔ ۲۴رجب کی شب، ۶۷۶هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: طبقات الشافعیۃ الکبری، تاج الدین سبکی: ۸/۳۹۵، طبقات الشافعیین، ابن کثیر، ص: ۹۱۳)
32۔ ان کانام : ابراہیم بن عمر بن ابراہیم شیخ برہان الدین جعبری اور کنیت : ابو اسحاق ہے۔ ۶۴۰هـ کی حدود میں پیدایش ہوئی۔ آپ فقیہ، قاری اور کئی فنون کے ماہر تھے۔ قراءات، حدیث اور اسماے رجال میں آپ کی تصانیف ہیں۔ ماہ رمضان، ۷۳۲هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: طبقات الشافعیۃ، تاج الدین سبکی : ۹/۳۹۹)
33۔ آپ کا نام : بدر الدین محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعہ، کنانی حموی ہے۔ مصر کے چیف جسٹس رہے۔ ۶۳۹هـ میں ولادت ہوئی۔ بہت سے علوم حاصل کیے اور بہت سے فنون میں لکھا۔ مدرسۂ کاملیہ وغیرہ میں تدریس وحدیث پڑھانے میں مشغول رہے۔ ۷۳۳هـ میں وفات ہوئی۔ (حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر والقاہرۃ، سیوطی : ۱/۴۲۵)
34۔ ان کا نام : حسین بن محمد بن عبد اللہ شرف الدین طیبی ہے۔ حدیث، تفسیر و علم بیان کے عالم تھے۔ وراثت و تجارت کی بنا پر بڑے صاحب ثروت تھے۔ اپنا مال بھلائی کے کاموں خرچ کردیا، یہاں تک کہ آخری عمر میں فقیر ہوگئے۔ بدعتی لوگوں پر سختی سے تنقید کرتے۔ طلبہ ٔ علم کو ہمیشہ پڑھایا۔ بلاغت، تفسیر و حدیث میں ان کی تالیفات ہیں۔ (دیکھیے: الدررالکامنہ، ابن حجر عسقلانی : ۲/۶۸ و ۶۹، کشف الظنون، حاجی خلیفہ: ۱/۷۲۰)
35۔ ان کا نام علاء الدین، علی بن عثمان بن ابراہیم بن مصطفی ماردینی ہے۔ ۷۸۳هـ میں ولادت ہوئی۔ فقہ، اصول اور حدیث کے امام تھے۔ ہمیشہ مصروف اور دوسروں کی علمی پیاس بجھانے میں لگے رہتے۔ ان کی تصانیف انوکھی ہیں، مثال کے طور پر، مختصر الہدایہ، مختصر علوم الحدیث، الرد علی البیہقی۔ مصر میں قضا کے عہدے پر فائز رہے۔ محر الحرام، ۷۴۵هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر والقاہرۃ، سیوطی: ۱/۴۶۹)
36۔ دیکھیے: ص۸۷۔
37۔ ان کا نام اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیر بن درع ہے۔ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی مولفات میں ’’التکمیل، احکام التنبیہ، طبقات الشافعیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ۷۰۱هـ میں پیدا ہوے اور ۷۷۴هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: ذیل التقیید فی رواۃ السنن والاسانید، ابو طیب مکی: ۱/۴۷۱)
38۔ ان کانام : سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد بن محمد انصاری ہے۔ ۷۲۳هـ ولادت ہوئی۔ جوانی میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہوگئے۔ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ تصانیف انھی کی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں : ’’شرح بخاری، شرح العمدۃ، الاشباہ والنظائر، وغیرہ شامل ہیں۔ ماہ ربیع الاول ۸۰۴هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر والقاہرۃ، سیوطی: ۱/۴۳۸)
39۔ آپ کامکمل نام: طاہر بن حسن بن عمر بن حسن بن عمر بن حبیب بن شریح حلبی، زین الدین ابوالعز ابن بدرالدین ہے۔ قصیدۂ بردہ کی ایک شرح لکھی۔ اپنے والد کی ’’تاریخ‘‘ پر انھی کے انداز میں تکملہ لکھا، تلخیص المفتاح کو نظمایا۔ ماہ ذی الحج ۸۰۸هـ میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: انباءالغمر بابناء العمر، ابن حجر عسقلانی: ۲/۳۳۸)
40۔ ۲/۳۳۸
41۔ دیکھیے: لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلوي الأصفوني ثم المكي الشافعي، ن: دار الكتب العلمية، ط الأولى: 1419هـ - 1998م، (صـ: 150)، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، ن: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، (4/173)، تاریخ اشاعت مذکور نہیں۔
امام ابن دقیق العید کا مکمل نام: محمد بن علی بن وہب بن مطیع اور کنیت ابوالفتح ہے۔ ابن دقیق العید کے نام سے مشہور ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے۔ مصر کے رہنے والے تھے۔ آپ چیف جسٹس اور اپنے زمانے کا بڑا نام تھے۔ بہترین محدث، صاحب تحقیق فقیہ واصولی، ادیب، شاعر، نحوی، بہت زیادہ عقل مند، خاموش طبع، زہد میں کامل، دین پر شدت سے عامل، راتوں کو ہمیشہ جاگ کر مطالعے میں مگن اور سخی انسان تھے۔ آپ نے اچھوتی تصانیف چھوڑیں، مثال کے طور پر: الامام، الالمام، علوم الحدیث، شرح عمدۃ الاحکام، شرح مقدمۃ المطرز فی اصول الفقہ، اربعین فی الروایۃ عن رب العالمین، شرح مختصر ابن الحاجب۔ (فوات الوفیات، محمد بن شاکر صلاح الدین: ۳/۴۴۳)
42۔ ان کانام محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن عبد اللہ اور کنیت ابوعبد اللہ ہے۔ قرآن کے قاری اور ذہبی کے لقب سے مشہور ہیں۔ حدیث کا علم حاصل کیا، تصنیف کے کام سے وابستہ رہے، تاریخ کے موضوع پر کتابیں لکھیں، احادیث کی تصحیح اور ان کی علل کو واضح کیا۔ قراءات سبعہ محمد بن عبد العزیز دمیاطی اور محمد بن منصور حارثی سے پڑھیں۔ خیرخواہی میں مشہور تھے۔ متواضع، اچھے اخلاق کے مالک، عبادت گزار اور خوش کلام تھے۔ ان کی عمدہ تصانیف ہیں، مثال کے طور پر: میزان الاعتدال، الکاشف، الموقظۃ وغیرہ۔ ۷۴۸هـ دمشق میں وفات ہوئی۔ (دیکھیے: معجم الشیوخ، تاج الدین سبکی: ص:۳۵۴)
43۔ ان کا نام : علی بن محمد بن علی حسینی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ شریف جرجانی اور سید شریف کے لقب سے مشہور تھے۔ فلسفہ، تفسیر، منطق کے ماہر اور دیگر علوم سے بھی وابستگی رکھتے تھے۔ جرجان میں تعلیم حاصل کی۔ مصر جا کر بابرتی اور مبارک شاہ وغیرہ سے پڑھا۔ یہاں آپ کا قیام چار سال رہا۔ آخر میں شیراز کو اپنا وطن بنا لیا۔ آپ کی تقریبا ۵۰ تالیفات ہیں: مثال کے طور پر، تفسیر الزہراوین، بیضاوی کا حاشیہ اور زمخشری کی کشاف کا حاشیہ۔ ۸۱۶هـ میں وفات ہوئی۔ (معجم المفسرین، عادل نویہض: ۱/۳۸۰)
44۔ ان کا نام محمد بن عبد الرحمن، شمس الدین سخاوی ہے۔ تاریخ دان، حدیث، تفسیر وادب کے عالم تھے۔ قاہرہ میں پیدا ہوے اور مدینہ میں فوت ہوے۔ ملکوں کے لمبے اسفار کیے۔ ۲۰۰ کے قریب کتابیں لکھیں۔ آپ کی مشہور کتابیں یہ ہیں: ’’الضوء اللامع فی اعیان القرن التاسع‘‘ ۱۲ جلد، شرح الفیۃ العراقی اور المقاصد الحسنۃ۔ ۹۰۲هـ میں خالق ازل کو لبیک کہا۔ (الاعلام، زرکلی : ۶/۱۹۴)
45۔ ۱/۱۵۶
46۔ ان کا نام : جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر بن محمد بن سابق الدین خضیری سیوطی ہے۔ آپ حافظ حدیث، مورخ و ادیب تھے۔ ۶۰۰ کے قریب کتابیں لکھیں۔ بعض کتابیں بڑی ہیں اور بعض چھوٹے رسالوں کی شکل میں ہیں۔ قاہرہ میں یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے۔ چالیس سال کی عمر ہوئی تو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اپنی جان پہچان والوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا، گویا کسی کو جانتے ہی نہیں۔ اسی زمانے میں آپ نے اپنی اکثر کتابیں لکھیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں الاتقان فی علوم القرآن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی اور المزہر فی اللغۃ شامل ہیں۔ ۹۱۱هـ وفات ہوئی۔ (دیکھیے: الاعلام، زرکلی : ۳/۳۱۰)
47۔ ان کا نام : عمر (یا طہ ) بن محمد بن فتوح بیقونی ہے۔ مصطلح الحدیث کے عالم تھے۔ دمشق کے رہنے والے اور شافعی مسلک سے تعلق تھا۔ منظومۂ بیقونیہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ محمد بن عثمان میر غنی وغیرہ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ ۱۰۸۰هـ وفات پائی۔ (الاعلام، زرکلی : ۵/۶۴)
48۔ ان کا نام : محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد حسنی ہے۔ سبل السلام جیسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اپنے آباء واجداد کی طرح ’’امیر‘‘ کے لقب سے مشہور ہیں۔ مجتہد اور بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد بھی زاہد اور فاضل انسان تھے۔ صنعاء میں علامہ زید بن محمد بن حسن اور علامہ صلاح اخفش و دیگر علما سے علم حاصل کیا۔ ۱۱۸۲هـ وفات ہوئی۔ (الاعلام، زرکلی : ۸/۵۷۵)
49۔ ان کا نام : علی بن سلطان محمد، نور الدین ملاہروی قاری ہے۔ حنفی فقیہ تھے۔ اپنے زمانے میں علمی صدارت کے حامل تھے۔ ہرات شہر میں پیدا ہوے۔ اس کے بعد مکہ چلے گئے اور وہیں فوت ہوے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہر سال قراءات وتفسیر سے مزین ایک قرآن پاک لکھ کر اسے بیچ دیتے اور اسے حاصل ہونے والی رقم انھیں پورے سال کے لیے کافی ہو جاتی۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں۔ ان میں تفسیر القرآن (تین جلد)، الاثمار الجنیۃ فی اسماء الحنفیۃ، الفصول المہمۃ، (فقہ کے موضوع پر)، مناسک، شرح مشکاۃ المصابیح، شرح مشکلات الموطا، شرح الشفاء، شرح حصن حصین (حدیث کے موضوع پر)، شر ح الشمائل، شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۱۰۱۴هـ ہوئی۔ (الاعلام، زرکلی: ۵/۱۲)
50۔ ان کا نام : جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم ابوالفرج ہے۔ کئی علوم سے وابستگی تھی۔ ملک شام میں فنون ادب اور علم دین میں مہارت کے لحاظ سے امام مانے جاتے تھے۔ پیدائش اور وفات دونوں دمشق میں ہوئی۔ عقیدے کے اعتبار سے سلفی اور تقلید کے منکر تھے۔ ادب، تفسیر اور شریعت اسلامی میں عمومی اور خصوصی لیکچرز دیے۔ مجلات اور اخباروں میں بہت سے مقالات لکھے۔ بہت سی مفید تالیفات آپ کی یادگار ہیں۔ ۲۳جمادی الاولی ۱۳۳۲هـ میں وفات ہوئی۔ (موسوعۃ مواقف السلف فی العقیدۃ والمنہج والتربیۃ، ابو سہل مغراوی: ۹/۱۸۶)
51۔ ان کا نام : طاہر بن محمد بن صالح بن احمد بن موہب سمعونی، جزائری ہے۔ دمشق میں پیدا ہوے اور وہیں پلے بڑھے۔ مدرسہ جقمقیہ میں داخل ہوے۔ استاد عبد الرحمن بستانی سے علم حاصل کیا اس کے بعد علامہ عبد الغنی غنیمی میدانی کے ساتھ ان کی وفات تک وابستہ رہے۔ دمشق میں مالکی مذہب کے فقیہ تھے اور شام کے مفتی۔ آپ کی تالیفات میں الجواہر الکلامیۃ فی ایضاح العقیدۃ الاسلامیۃ، تنبیہ الاذکیاء فی قصص الانبیاء، توجیہ النظر الی علم الاثر اور التبیان لبعض المباحث المتعلقۃ بالقرآن، شامل ہیں۔ دمشق میں ۱۳۳۸هـ میں وفات ہوئی۔ (موسوعۃ السلف فی العقیدۃ والمنہج والتربیۃ، ابو سہل مغراوی: ۹/۱۹۳)
52۔ ان کا نام : محمد بن محمد بن سویلم ابو شہبہ ہے۔ مصر کے گاؤں ’’منیہ جناج‘‘ میں ۱۳۳۲هـ کو پیدا ہوے۔ مصر و دیگر ملکوں کے بلند پایہ علمی، دینی و ادبی مجلات میں لکھا۔ بہت سے لیکچرز دیے اور بہت سی علمی محافل میں شریک رہے۔ علوم قرآن، سنت نبوی، فقہ، شریعت، سیرت نبوی، مستشرقین، عیسائی مبلغین اور ملحدین کے رد پر کتابیں لکھیں۔ آپ کی تالیفات میں الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، السیرۃ النبویۃ علی ضوء القرآن والسنۃ، الوسیط فی علوم ومصطلح الحدیث، دفاع عن السنۃ ورد شبہ المستشرقین، شامل ہیں۔ ۱۴۰۳هـ میں وفات ہوئی۔ http://shamela.ws/index.php/author/1378
53۔ ان کا نام : ابو حفص محمود بن احمد بن محمود طحان نعیمی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا سادات خاندان سے تعلق ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ شام کے شہر حلب کے رہنے والے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ محمد ابو زہو رحمہ اللہ شامل ہیں، جنھوں نے ’’الحدیث والمحدثون ‘‘ کے نام سے کتاب لکھی۔ استاد محمود طحان کی کتابوں میں تیسیر مصطلح الحدیث، اصول التخریج ودراسۃ الاسانید شامل ہیں۔ http://shamela.ws/index.php/author/1269
54۔ آپ کا نام : عبد اللہ بن یوسف بن عیسی بن یعقوب جدیع عنزی ہے۔ آپ نے بڑی تعداد میں مقالے لکھے۔ یورپین کونسل براے افتاء و تحقیق کے رکن ہیں۔ لیڈز گرینڈ مسجد کے شرعی مشیر ہیں۔ آپ کی تالیفات میں تیسیر اصول فقہ اور علل الحدیث شامل ہیں۔ http://muntada.islamtoday.net/t37387.html
55۔ آپ کانام : نور الدین عتر ہے۔ ۱۹۳۷ء میں شہر حلب میں پیدا ہوے۔ آپ کا گھرانہ علم، نیکی اور کتاب و سنت سے جڑا ہوا تھا۔ جامعہ ازہر سے پڑھا۔ چالیس سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان میں مشہور کتابیں یہ ہیں: منہج النقد فی علوم الحدیث، الامام الترمذی والموازنۃ بین جامعہ وبین الصحیحین، اصول الجرح والتعدیل۔ دمشق میں ازہر یونی ورسٹی کی شاخ میں علوم القرآن وحدیث کے رئیس رہے۔ (دیکھیے: محمد حميد الله وأمين التراث الإسلامي في الغرب، سيد عبد الماجد الغوري، صـ۹)
ترجمہ،تلخیص و حواشی: فضل الرحمٰن محمود