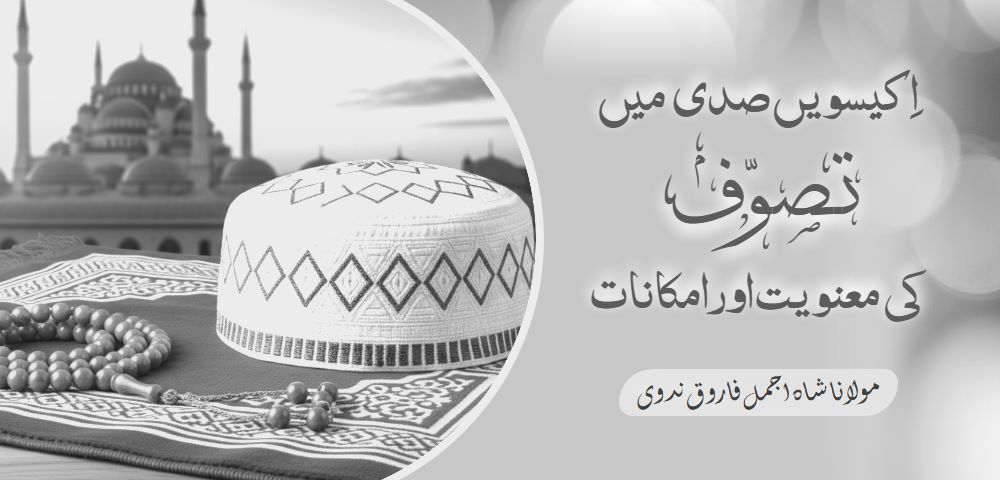تمہید
تصوف کے متعلق یہ بحث اب فضول ہو چکی ہے کہ کون سا تصوف اسلامی ہے؟ اور کون سا غیر اسلامی؟ اس موضوع پر اتنا لکھا جا چکا اور اس مسئلے کی وضاحت اس کثرت کے ساتھ کی جا چکی کہ اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تصوف کے نام پر جو خرافات، غیر اسلامی اعمال اور لغو چیزیں مفاد پرست اور مادہ پرست لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، اُنھیں تصوف کہنا ہی غلط ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں پھیلی بدکاریوں کی بنا پر اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، اُسی طرح جاہل اور مادہ پرست ٹولے کی حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ابوالمجاہد زاہد نے بہت خوب کہا ہے:
تصوف اُس جگہ سے غیر اسلامی تصوف ہے
جہاں سے ساتھ چھوڑا ہے تصوف نے شریعت کا
قرونِ اولیٰ سے لے کر عہدِ جدید تک کے تمام علما و صالحین اس بات کی وضاحت کرتے آئے ہیں کہ تصوف کا مقصد رضائے الٰہی اور اس کے حصول کا راستہ اتباعِ سنت ہے۔ رسول کریم ﷺ کی راہ سے ہٹ کر جو راہ بھی اختیار کی جائے گی، وہ ناقابلِ قبول بھی ہو گی اور باعثِ عذاب بھی۔ اس سلسلے میں حضرت ذوالنون مصریؒ کا یہ قول ہماری رہنمائی کرتا ہے:
من علامات المحب لللہ عزوجل متابعۃ حبیب اللہ ﷺ فی أخلاقہ و أفعالہ وأوامرہ وسننہ۔1
’’اللہ سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اخلاق، اعمال، احکام اور ہر چیز میں اللہ کے محبوب کی پیروی کرتا ہو۔‘‘
اسی طرح حضرت جنید بغدادی کا یہ ارشاد بھی بہت فیصلہ کن ہے:
مذھبنا ھذا مقید بأصول الکتاب والسنۃ، و علمنا ھذا مشید بحدیث رسول اللہ ﷺ۔2
’’ہمارا یہ راستہ کتاب و سنت کے اصول سے بندھا ہوا ہے اور یہ علم احادیثِ رسول سے وابستہ ہے۔‘‘
تصوف کی ضرورت
کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی روح پاک ہو چکی، اس کا دل صاف شفاف ہو چکا، اُسے رضائے الٰہی کی نعمت مل چکی اور اب کبھی یہ چیزیں اُس سے دور نہیں ہو سکتیں۔ جب یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تو اِن چیزوں کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش کی اہمیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ روح کی پاکیزگی، قلب کی صفائی اور رضائے الٰہی کی کوشش ایسے اعمال ہیں، جو انسان کی موت تک جاری رہنے چاہییں۔ اُس وقت تک، جب تک کہ انسان کے لیے اعمالِ خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ کیوں کہ:
براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے
ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تصوف وہی چیز ہے، جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں تزکیہ اور حدیثِ نبوی کی اصطلاح میں احسان کہا گیا ہے۔ اس لیے کسی کو تصوف کے نام پر کوئی اعتراض ہو تو اِن دونوں ناموں میں سے کوئی ایک یا دونوں اختیار کر لے۔ لیکن اس کی ضرورت یا عدمِ ضرورت پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ تزکیہ و احسان کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر دور میں تھی، ہے اور رہے گی۔3
مزید لکھتے ہیں: احسان اور فقہ باطن سب علمی و شرعی حقائق اور دین کے مسلّمہ اصول ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر اہلِ تصوف اس مقصد کے حصول کے لیے (جس کو ہم تزکیہ و احسان سے تعبیر کرتے ہیں) کسی خاص اور متعین راستے یا شکل پر اصرار نہ کرتے (اس لیے کہ زمان و مکان اور نسلوں کے مزاج اور ماحول کے ساتھ اصلاح و تربیت کے طریقے اور ان کے نصاب بھی بدلتے رہتے ہیں) اور وسیلے کے بجائے مقصد پر زور دیتے تو اس مسئلے میں آج سب یک زبان ہوتے اور اختلاف کا سر رشتہ ہی باقی نہ رہتا۔ سب دین کے اس شعبے اور اسلام کے اس رکن کا جس کو ہم تزکیہ یا احسان یا فقہ باطن کہتے ہیں، صاف اقرار کرتے اور اس بات کو بلا تأمل قبول کرتے کہ وہ شریعت کی روح، دین کا لب لباب اور زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ کہ جب تک اس شعبے کی طرف کما حقہ توجہ نہ کی جائے، اس وقت تک کمال دین حاصل نہیں ہو سکتا اور اجتماعی زندگی کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ صحیح معنی میں زندگی کا لطف آسکتا ہے۔4
دو بنیادی سوالات
تصوف کی اہمیت اور ضرورت واضح ہونے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کی عصری معنویت کیا ہے؟ دوڑ بھاگ سے بھری ہوئی زندگی میں ہم کسی کو تصوف کی اہمیت کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی روحانی تربیت کے لیے کچھ وقت نکالو۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور سرمایہ داری کے اس دور میں ہم کسی کو تصوف کے اعمال کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیا آج کا انسان یہ سمجھنے پر آمادہ ہوگا کہ تصوف اُس کی زندگی کی ایک اہم بلکہ سب سے اہم ضرورت ہے؟ اگر کوئی شخص اس کی تسلیم کر لے تو ہمیں اُس کی روحانی تربیت کے لیے کیا طریقۂ کار اختیار کرنا ہوگا؟ نہ اب اہلِ حق کی خانقاہیں عام ہیں کہ انسان وہاں جا کر کچھ وقت لگائے اور اپنی روحانی تربیت کا انتظام کرے۔ جو چند خانقاہیں موجود ہیں، وہاں جا کر کچھ وقت لگانا عام انسان کے لیے نہایت مشکل ہے۔ گویا اب ہمارے سامنے دو بنیادی سوالات ہیں:
۱۔ کیا اکیسویں صدی کے انسان کے لیے تصوف کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟
۲۔ اکیسویں صدی میں ایک عام انسان کی اصلاحِ باطن کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟
آئیے! ان دونوں سوالات پر قدرے تفصیل سے گفتگو کریں۔
موجودہ انسانی مسائل اور تصوف
آج کے انسان کے تمام روحانی امراض کی جڑ مادیت پرستی ہے۔ روحانی وجود کی حفاظت کے لیے روحانیت کی تقویت ضروری ہے، لیکن آج کے انسان کو اس کے مواقع بہت کم حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں روحانی وجود خال خال نظر آتے ہیں۔ غور کیا جائے تو مادیت پرستی کا یہ مرض تین شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے: (۱) بناوٹی زندگی (۲) داخلی اضطراب (۳) فساد فی الارض۔ یہ تینوں شکلیں اپنا مستقل وجود بھی رکھتی ہیں اور ایک دوسرے سے بندھی ہوئی بھی ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے ظاہر کو دکھاوے اور بناوٹ کا عادی بناتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی روح مردہ، ضمیر بے دم اور دل بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس روحانی موت کا نتیجہ فساد فی الارض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی محدود پیمانے پر اور کبھی وسیع ترین پیمانے پر۔
۱۔ بناوٹی زندگی
بناوٹی زندگی بظاہر کوئی بڑی مصیبت نہیں لگتی، لیکن معمولی غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ موجودہ دنیا کے اکثر امراض کی جڑ ہے۔ امریکا سے نکلنے والے مشہور جریدے Psychology Today نے ۲ جولائی ۲۰۱۸ کو اپنی ویب سائٹ پر پروفیسر کلیر براؤن (Prof. Clair Brown) کا ایک تحقیقی مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون میں کئی اہم اشارات کیے گئے ہیں۔ مضمون نگار امریکا میں بیٹھ کر اس نتیجے تک پہنچی ہیں کہ دکھاوے کی زندگی سے انسان کو بہت نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ زندگی انسانیت کو مختلف ذہنی، جسمانی اور سماجی مصیبتوں سے دوچار کر رہی ہے۔ اس مضمون کی کچھ سطریں ملاحظہ کیجیے:
Not much from a happiness or social welfare viewpoint, as Buddhist economics explains. While a person shows off their self-importance, they are still wanting more because another rich person has an even longer yacht or bigger house. The valuation of consumption rests on comparing ourselves to one another. Thorstein Veblen, the 20th Century economist who coined the terms “conspicuous consumption” and “invidious comparisons,” pointed out how individuals use luxury goods to show off their status. Veblen observed that people were living on treadmills of wealth accumulation, competing incessantly with others but rarely increasing their own well-being. This means that when inequality increases, we all feel less well-off even if our income has not gone down. When the rich get even richer and the rest of us don’t get more, our stagnant income and lifestyles seem diminished. Over the past four decades, economic growth has mostly gone to the top 5% of households, and this growth begets more inequality, without increasing social welfare as it exacerbates invidious comparisons.5
’’صرف خوشی یا سماجی بہبود کے نقطۂ نظر سے نہیں، جیسا کہ بدھ مت کی معاشیات بیان کرتی ہے، بلکہ عام طور پر جب کہ ایک شخص اپنی خود کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، تو دراصل وہ اس سے بھی زیادہ کا طالب ہوتا ہے، کیوں کہ اس کے سامنے دوسرا امیر شخص ہوتا ہے، جس کے پاس اس سے بھی لمبی یاٹ یا بڑا گھر ہوتا ہے۔ کھپت کی تشخیص خود کو ایک دوسرے سے موازنہ کرنے پر منحصر ہے۔ Thorstein Veblen بیسویں صدی کے ماہر معاشیات جنھوں نے ''spicuous consumption'' اور ''invidious comparisons'' جیسی اصطلاحات وضع کیں، انھوں نے اس بات کی نشان دہی کی ہے کہ لوگ اپنی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کس طرح پر تعیش اشیا کا استعمال کرتے ہیں۔ ویبلن نے بتایا کہ لوگ دولت جمع کرنے کی ٹریڈمل پر زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی اپنی فلاح و بہبود میں اضافہ کر پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عدمِ مساوات بڑھ جاتی ہے، تو ہم سب اپنی کم خوش حالی محسوس کرتے ہیں، چاہے ہماری آمدنی کم نہ ہوئی ہو۔ جب امیر اور بھی امیر ہو جاتے ہیں اور ہم میں سے باقی لوگ زیادہ امیر نہیں ہوتے ہیں تو ہماری رکی ہوئی آمدنی اور طرز زندگی کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلی چار دہائیوں کے دوران، اقتصادی ترقی زیادہ تر گھرانوں میں زیادہ سے زیادہ 5% تک پہنچی ہے اور یہ ترقی سماجی بہبود میں اضافہ کیے بغیر، مزید عدمِ مساوات کو جنم دے رہی ہے کیوں کہ یہ ناگوار مقابلے کو بڑھاتی ہے۔‘‘
اس اقتباس کی روشنی میں یہ سمجھنا مشکل نہیں رہ جاتا کہ آج کے انسان نے اپنے اوپر بناوٹ کا ایک خول چڑھا لیا ہے۔ اس کی ساری تگ و دو اس خول کی سجاوٹ اور بناؤ سنگار میں صرف ہو رہی ہے۔ اس کا اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، بولنا چالنا، تجارت یا ملازمت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، ملنا جلنا، حتیٰ کہ سوچنا سمجھنا بھی دوسروں کو پیش نظر رکھ کر ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ ان سوالات کے اردگرد اس کی پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ وہ اس بناوٹ کے لیے اپنا مال دولت زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے دن رات ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر ملنے والی خوشی اور دوستوں یاروں کے ساتھ کی جانے والی موج مستی سے وہ محروم رہتا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متعدد ذہنی، فکری اور جسمانی امراض کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی بے شمار تحقیقات کے مطابق اس طرح کی غیرفطری زندگی گزارنے کی وجہ سے دورانِ خون کا بڑھنا (High Blood pressure)، شکر (Sugar)، امراض قلب (Heart diseases)، پیٹ کی متعدد بیماریاں، مختلف طرح کے سر درد، جنسی مسائل، بے خوابی، گردن اور ٹانگوں کے امراض اور اس طرح کے دسیوں امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ امراض سننے میں تو بہت عام معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ان امراض کے مستقل شکار رہتے ہیں، وہ کس صورت حال سے دوچار رہتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ ان امراض سے انسان جن مسائل کا شکار ہے، وہ تو اپنی جگہ ہیں، ان کے نتیجے میں خرچ ہونے والے سیکڑوں کروڑ کے مالی وسائل بھی انسانیت کے لیے سوہانِ روح سے کم نہیں ہیں۔
اس بڑے انسانی مسئلے کو سامنے رکھ کر جب ہم صوفیائے کرام کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اُن کے ہاں مختلف ناحیوں سے اس بنیادی مسئلے کا حل موجود ہے۔ صوفیائے کرام کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں توکل علی اللہ، زہد فی الدنیا، استغنا، دنیا اور اہل دنیا سے بے زاری، حب فی الآخرۃ، مادے کی بے حیثیتی اور اس طرح کی دوسری تعلیمات سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، جو انسان کو ظاہر سے باطن کی طرف، تکلف سے بے تکلفی کی طرف، بناوٹ سے حقیقت کی طرف، حرص و ہوس سے قناعت و توکل کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو انسان ان اعلیٰ تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بناوٹی زندگی اور اس کی لعنتوں سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے دل و دماغ میں ایسا سکون و اطمینان رچ بس جاتا ہے کہ اسے دنیا کی رنگا رنگی اور بناؤ سنگار سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہمیں روشنی دکھاتا ہے:
الزھد علی ثلاثۃ أوجہ، ترک الحرام وھو زھد العوام، والثانی ترک الفضول من الحلال وھو زھد الخواص، والثالث ترک ما یشتغل العبد عن اللہ تعالیٰ وھو زھد العارفین۔6
’’زہد تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حرام کاموں کو چھوڑنا، یہ عوام کا زہد ہے۔ دوسرے حلال چیزوں میں سے بھی ضرورت سے زائد چیزوں کو چھوڑنا، یہ خواص کا زہد ہے۔ تیسرے ہر اس چیز کو چھوڑنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، یہ عارفین کا زہد ہوتا ہے۔‘‘
اگر آج کا انسان زہد کے ان تین مراحل میں سے صرف پہلے مرحلے کا اہتمام کر لے تو بھی اس کے مسائل بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے زہد کا تو پوچھنا ہی کیا۔
۲۔ داخلی اضطراب
انیسویں صدی میں دنیا نے ایک طرف صنعت و ایجادات کے حوالے سے برق رفتاری کے ساتھ ترقی کرنی شروع کی، تو دوسری طرف انسان کو ایک نئے مرض سے سامنا کرنا پڑا۔ تنہائی اور اکیلا پن (Loneliness)۔ یہ مرض اس سے پہلے بھی پایا جاتا تھا، لیکن صرف انفرادی طور پر یا بہت محدود پیمانے پر۔ انیسویں صدی میں اس مرض نے شدید وسعت اختیار کر لی۔ اب دنیا کا بڑا حصہ اس سے متأثر ہوگیا۔ اس کے اثرات نے بھی خطرناک رخ اختیار کرلیا۔7
دراصل صنعتی انقلاب کے بعد انسان کی پوری زندگی نے مشینی رخ اختیار کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا کام مشینوں پر منحصر ہوگیا۔ ساتھ ہی دولت کی ریل پیل نے ہر انسان کے سر پر مادیت کا نشہ سوار کر دیا۔ انسان کا مقصد کمانا کھانا اور مادیت کی راہ میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگانا بن گیا۔ مادی لحاظ سے بڑے لوگوں کو خدا بنا دیا گیا اور ان کی خوش نودی کے لیے سب کچھ ہنسی خوشی کرنا عقل مندی تصور کیا جانے لگا۔ خودداری، انسانی ہم دردی، غریبوں کی دل داری اور اعزہ و اقارب کی خبرگیری کو غیر ضروری اور نادانی کے کام سمجھا جانے لگا۔
گویا انسان خود بھی چلتی پھرتی مشین بن گیا۔ ایسی مشین جس میں نہ دل ہوتا ہے اور نہ احساس۔ وہ تو دن رات اپنے مالک کے اشارے کے مطابق کام میں لگی رہتی ہے۔ مالک اسے کچھ آرام دے دے یا اس میں تیل وغیرہ ڈال دے تو اس کا احسان ہے۔ اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ مالک کی مرضی کے خلاف زبان ہلا سکے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ مشین ایک دن بند ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی نہیں چل پاتی۔ اگلے ہی دن مالک اس کو کوڑے کے بھاؤ بیچ کر دوسری مشین لے آتا ہے۔ اس پورے نظام میں پسنے والا انسان شدید اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ روحانی بے چینی، اندرونی اضطراب، بہت کچھ ہونے کے باوجود شدید خالی پن کے احساس اور یاس و قنوط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
پھر یہ چیزیں جسمانی امراض کی شکل اختیار کرتی ہیں تو سخت ذہنی دباؤ، قلبی امراض اور متعدد نفسیاتی امراض اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جو لوگ ان امراض کے لیے کسی ڈاکٹر کا رخ نہیں کرتے یا اپنے احساسات کو زیادہ عرصے تک دبائے رہتے ہیں وہ نشے کی دنیا میں اپنی پناہ ڈھونڈتے ہیں یا اپنی زندگی کے خاتمے کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال ہونے والے خود کشی کے واقعات اور نشے کی بڑھتی ہوئی رفتار کے پیچھے یہی داخلی اضطراب کارفرما ہے۔8
ان مسائل سے جوجھتا ہوا انسان جب تصوف کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سابقہ ایک رہنما سے پڑتا ہے۔ جسے تصوف کی اصطلاح میں مرشد یا پیر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو حتی الامکان اپنے اندرون کو صاف کر چکنے کے باوجود خود کو ناقص سمجھتا ہے اور دوسروں کو پیار محبت سے صحیح راہ دکھاتا رہتا ہے۔ اس کا دروازہ خلق خدا کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ ہر طالب کی باتیں سکون سے سنتا ہے اور پھر اس کی کچھ رہنمائی کرتا ہے۔ اکیلے پن اور خالی پن کے شکار انسان کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی اسے راہِ سلوک پر گامزن ہونے سے پہلے ہی مسائل کا حل اور غموں کا مداوا مل جاتا ہے۔
اس کے بعد وہ مرشد کامل سے حسب توفیق استفادہ کر کے سکون و اطمینان کی فضا میں سانس لینے لگتا ہے۔ مرشد کے پاس اسے ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کے قادر مطلق ہونے اور باقی سب کے عاجز ہونے کا سبق ملتا ہے۔ مراقبے اور مجاہدے کے ذریعے اسے اللہ کے باقی ہونے اور باقی سب کے فانی ہونے کا علم ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ محبت و موانست، خلق خدا کی خدمت اور ان کے ساتھ ہم دردی کو سب سے عظیم عبادت جاننے کا درس ملتا ہے۔ اپنے رشتے داروں، پڑوسیوں اور دوستوں یاروں کی خبرگیری، عیادت، تہنیت، تعزیت اور ان کے ساتھ ہنستے بولتے کچھ وقت گزارنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تمام تعلیمات اس کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہیں۔ اس طرح وہ مایوس انسان اپنی روح کو پرسکون اور جسم کو صحت مند کر کے خالق کائنات کے نظام فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔
۳۔ فساد فی الارض
موجودہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ فساد فی الارض ہے۔ یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلائے جانے والے مختلف بگاڑوں کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔9 اس زمین پر برپا ہونے والا پہلا فساد وہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کا خون بہا کر پیدا کیا تھا۔10 آخری فساد قیامت کے بالکل قریب مسیحِ دجال کے ذریعے برپا کیا جائے گا۔11 اس پہلے اور آخری فساد کے درمیان واقع ہونے والا ہر وہ واقعہ جس سے انسانیت مصیبت میں گرفتار ہو، اسے فساد فی الارض کہا جاتا ہے۔ کفر و شرک، لوٹ مار، کالابازاری، دھوکہ دہی، چوری ڈکیتی، زنا کاری، قتل و غارت گری، دنیوی فائدے کے لیے ہونے والی جنگیں، دولت کے نشے میں انسانیت کو نشے اور جنسیات کا عادی بنانا، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے نئے نئے موذی امراض پھیلانا یا بڑے بڑے گھوٹالے کرنا، میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانا، رشوت خوری، سودی کاروبار، جوا یا سٹے بازی، ظالمانہ ٹیکس اور اس طرح کی بے شمار چیزیں زمین میں فساد برپا کرنے میں شامل ہیں۔ ماضی قریب میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا پراسرار مرض Covid-19 بھی فساد فی الارض کی ایک شکل تھی۔ دنیا کے مٹھی بھر انسانوں پر فساد فی الارض کا دورہ پڑتا ہے اور وہ پوری انسانیت کو انتہائی نازک حالات سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس میں عام انسانوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی فسادی طاقتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ ان کے سجھائے ہوئے خطرناک راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہیں۔
تصوف کے اندر اس بات کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسان کو انسان بنائے۔ آدمیت کا سبق یاد دلائے۔ نفس پرستی کے راستے سے ہٹا کر خدا پرستی کی راہ پر لگائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس حسین دنیا کو جہنم کے بجائے جنت بنائے۔ تصوف میں خلق سے محبت، مخلوق کی خدمت اور ہر انسان کو اپنا بنانے کا جو درس بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہی درس فساد سے بھری اس دنیا کو جنت نما بنا سکتا ہے۔ یہ طاقت امن کے علم بردار کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں کہ دوسرے مذاہب امن کی دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن نہ تو پوری انسانیت کو ایک مرکز پر جمع کر سکتے ہیں اور نہ انسانوں کو عالمی بھائی چارے کا درس دے سکتے ہیں۔ یہ کام صرف اسلام کر سکتا ہے کہ سارے انسانوں کو وحدانیت کے محور کے گرد جمع کرے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا تصور دے کر رنگ، نسل، ذات اور علاقائیت کے ہر بت کو پاش پاش کر دے۔ شاید ہم برصغیر والے اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیوں کہ ہمارے پاس حضرت سید علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی، خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز اور ان جیسے بے شمار اولیا و اصفیا ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص نے ہزارہا ہزار بندگان خدا کو ان کے رب سے جوڑنے اور فساد فی الارض کو ختم کرنے کا کام نہایت وسیع پیمانے پر انجام دیا ہے۔
امکانات
عہد حاضر میں تصوف کی معنویت اور اہمیت و افادیت سمجھنے کے بعد اب یہاں دوسرا سوال سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں تصوف کے لیے کیا امکانات موجود ہیں؟ کیا آج کے انسان کے لیے تصوف کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل حل کر سکے؟ کیا تصوف کا سیکڑوں سالہ قدیم نظام اپنے اندر ایسی لچک رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ اکیسویں صدی کے بدحال انسان کے لیے لائقِ عمل بن سکے؟ اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ تصوف اسلام کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے۔ لہٰذا جس طرح اسلام کے اندر ہر دور اور زمانے کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اُسی طرح تصوف کے اندر بھی یہ صلاحیت بہ درجۂ اتم پائی جاتی ہے۔ لیکن تصوف کو آج کے انسانی مسائل کے لیے بہترین عملی حل کے طور پیش کرنا، اُس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جب تک کہ اسے عملی نہ بنا دیا جائے۔ اس بڑے مرحلے کو طے کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں:
۱۔ معاشرے میں تصوف کی پوزیشن واضح کی جائے۔ تصوف کے نام پر بددینی اور اسلام مخالف چیزوں کو فروغ دینے والوں کی سخت مذمت کی جائے۔ دنیا کو بتایا جائے کہ تصوف اِس گورکھ دھندے کا نام نہیں، بلکہ ایک پاکیزہ اسلامی تربیتی نظام کا نام ہے۔
۲۔ اپنے اندر وہ کشادہ دلی، مال و جاہ سے بے زاری، سخاوت، تواضع، نرمی اور جھکاؤ، اعتدال و میانہ روی اور خوش خلقی پیدا کی جائے ، جو ہر دور میں صوفیائے کرام کی شناخت رہی ہے۔
۳۔ خانقاہوں کے دروازے نئی نسل کے لیے کھول دیے جائیں۔ اس طور پر کہ انھیں خانقاہوں میں وحشت اور اجنبی پن محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے خانقاہوں کے ظاہری ماحول کو بھی مناسب بنانا ہوگا اور اہلِ خانقاہ کی وضع قطع اور اخلاق میں بھی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔
۵۔ خانقاہوں میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں، جن میں آج کا انسان دلچسپی محسوس کرے۔ مثلاً: آپ کے مسائل اور اُن کا حل، نوجوانوں کے مسائل: اسباب و علاج، تعلیم: کیوں اور کیسے؟، معاشی تنگی: اسباب اور حل، ذہنی الجھنوں کے اسباب اور علاج، روحانی بے چینی کے اسباب و علاج، گھریلو جھگڑے اور ان کا حل۔
۶۔ مذکورِ بالا موضوعات پر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، عالمی و علاقائی زبانوں میں دل کش گٹ اَپ کے ساتھ شائع کرنا۔ ساتھ ہی ان موضوعات پر آڈیو، ویڈیو مواد فراہم کرنا۔
۷۔ معروف و غیر معروف بزرگانِ دین کے احوال کو ہر ممکنہ وسیلے کے ذریعے گھر گھر پہنچانا۔
۸۔ ایسے آن لائن یا آف لائن پروگرام منعقد کیے جائیں، جن میں عوام کو اپنے احساسات پیش کرنے کا موقع بھی مل سکے۔ جیسے: روحانی، ذہنی اور فکری الجھنوں پر سوال جواب کا پروگرام۔
۹۔ اس طرح کے پروگرام خانقاہوں سے نکل کر تعلیمی اداروں اور دوسرے اہم مقامات پر منعقد کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔
۱۰۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل تصوف ، بالخصوص مشائخ و مرشدین اپنے اور عوام کے درمیان حائل اونچی دیواروں کو ڈھا دیں، تاکہ دوریاں ختم ہوں، شکوک و شبہات کے جالے جھڑ جائیں اور عوام کو بلاواسطہ مشائخ و مرشدین کی زندگیوں میں تصوف کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملے۔
یہاں اس بات کا اعتراف ضروری ہے کہ ان میں سے بہت سے اہم اقدامات مختلف معتبر خانقاہوں اور مستند مشائخ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ اس کے مثبت نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ان اقدامات کی رفتار بہت سست اور مقدار بہت کم ہے۔ اہلِ تصوف کو مذکور بالا تمام کام پوری قوت کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ ان شاء اللہ پھر عہدِ حاضر میں تصوف کی معنویت بھی واضح ہوگی اور بے چین انسان کو چین سکون بھی میسر آئے گا۔
خاتمہ
اکیسویں صدی میں تصوف کی معنویت اور امکانات کے متعلق اس مختصر جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکیسویں صدی میں اسلام کے نظامِ تزکیہ و احسان اور نظامِ تصوف و سلوک کے لیے کام کرنے کا وسیع میدان کھلا ہوا ہے۔ آج کے انسان کو پہلے سے کہیں زیادہ تصوف کی ضرورت ہے۔ اگلے زمانوں کا انسان صرف روحانی امراض کے علاج کے لیے تصوف سے وابستہ ہوتا تھا، آج کا انسان روحانی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بیمار ہو چکا ہے۔ بیماریاں بھی معمولی نہیں، مہلک اور تباہ کن۔ آج کے انسان کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں، اگر وہ خلوص دل کے ساتھ اس نظام کا تجربہ کر دیکھے۔ اس کی زندگی سکون و اطمینان سے بھر جائے۔ بے چینی اور اضطراب ختم ہوجائے۔ کیوں کہ دنیا کی بے حیثیتی، اخروی زندگی کی ہمیشگی کا یقین، مادے (Material) کے بے اصل ہونے، بہ ظاہر معمولی نظر آنے والے اخلاقی امراض کے انتہائی خطرناک ہونے کا یقین، ایک ذات کے مالک و حاکم ہونے اور باقی سب کے غلام و حقیر ہونے کا احساس، دنیا کی سب سے بڑی نعمت رضائے الٰہی کو سمجھنا اور اس کے حصول کو اپنی زندگی کا مدار اور محور بنانا، ایک خاص ترتیب کے ساتھ رشتے داروں، عزیزوں، پڑوسیوں، دوستوں، غریبوں، ناداروں، حتیٰ کہ جانوروں، پرندوں اور نباتات تک کے حقوق کی اہمیت ، انسان کو ایک فطری زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ شریعت کی روشنی میں ان تمام عقائد و اخلاق کی تربیت کا نام ہی تصوف ہے۔ عقائد کی پختگی اور اخلاق کی برتری ہی تصوف کا موضوع ہے۔ اگر انسانیت اس عظیم نظام سے وابستگی اختیار کر کے اپنا سفر آگے بڑھائے گی تو مادی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی بھی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ روحانی ترقی، جس کے بغیر مادی ترقیات انسان کے لیے آفت اور مصیبت بن چکی ہیں۔ بالکل اسی طرح، جس طرح روح کے بغیر جسم بے کار ہوتا ہے، اُسی طرح دنیا کی روحانی ترقی کے بغیر مادی ترقی کا کوئی مطلب نہیں۔
حوالہ جات / حواشی
- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم ابن ہوازن، الرسالۃ القشیریۃ فی علم التصوف، المکتبۃ التوفیقیۃ، قاہرہ، 2015، ص 40
- الرسالۃ القشیریۃ، حوالۂ سابق، ص 82
- ندوی، سید ابوالحسن علی، تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ، 1979،ص 13-16
- تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک، حوالۂ سابق، ص 16,17
- https://www.psychologytoday.com
- الرسالۃ القشیریۃ، حوالۂ سابق، ص232
- وکی پیڈیا کا مقالہ، بعنوان Loneliness
- اس موضوع پر بڑا لٹریچر وجود میں آچکا ہے۔ بیسیوں تحقیقاتی رپورٹیں انٹرنیٹ پر دست یاب ہیں۔ مثلاً Loneliness: Causes and Health Consequences کے موضوع پر Kendra Cherry کا مختصر مضمون https://www.verywellmind.com پر دیکھا جاسکتا ہے۔
- نمونے کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں: البقرہ 30,60,204-206، المائدہ 33,64، ہود 85، الرعد25
- المائدہ، آیت 31
- دجال کے سلسلے میں رسول اکرم ﷺ نے بہت تفصیل کے ساتھ انسانیت کو خبردار فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کی کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر صحیحین میں کتاب الفتن سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔