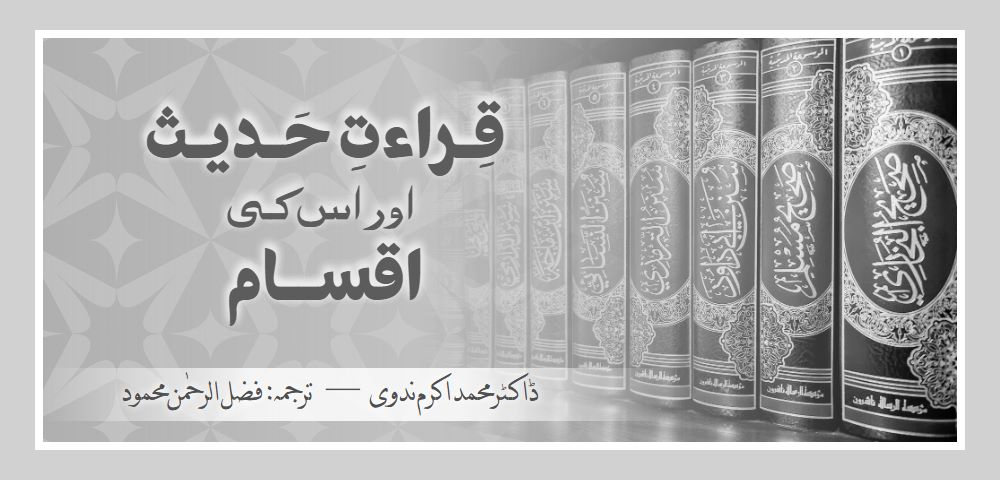ایک دفعہ شہر خدا، مکہ مکرمہ سنہ ۱۴۴۳ھ میں مجھے عربی خانوادے کے ایک صاحبِ علم و کرم کے گھر میں علما و محققین کی ایک مجلس میں حاضری کا موقع ملا۔ ان کے درمیان کتبِ حدیث کی قراءت کے بارے میں بحث چل نکلی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ قراءتِ حدیث کی اقسام اور اس کے مقاصد کا مکمل احاطہ نہیں کر پا رہے، ان کی آرا باہم ٹکرا رہی ہیں، اقسام کو آپس میں خلط ملط کر رہے ہیں، اور قراءتِ حدیث کے مختلف پہلؤوں اور انواع کو صحیح طریقے سے علاحدہ علاحدہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ قصہ طاقِ نسیاں کی نذر ہونے ہی لگا تھا کہ کچھ مبتدی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سکہ بند دوستوں کی شان گھٹانے میں لگے ہیں اور حدیث پڑھنے پڑھانے اور سماعِ حدیث میں مشغول اصحابِ علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ بیماری آگے بڑھ کر بھلے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو میں کبھی بھی ان کی تنقید کی پروا نہ کرتا اور نہ ہی یہ مقالہ لکھنے کے لیے تیار ہوتا۔
علوم و فنون کے حصول اور ان میں مہارت پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ بات کسی ذہین و ماہر اور باکمال عقل مند شخص سے پوشیدہ نہیں۔ علمِ حدیث انھی علوم و فنون کا حصہ ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ان تمام طریقوں کا خلاصہ تین قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے:
۱۔ مکمل تفصیل سے بحث و تحقیق کے ساتھ علم حدیث پڑھا جاے
۲۔ حدیث پڑھتے ہوے متوسط درجے کی تشریح کی جاے
۳۔ حدیث کی صرف تلاوت کی جاے
اب میں ان تینوں اقسام کی ناواقف یا تجاہلِ عارفانہ سے کام لینے والوں کے لیے تشریح کرتا ہوں:
قسم اول:
طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر حدیث کی مکمل کتاب یا اس کا کچھ حصہ پڑھے۔ استاد پڑھاتے ہوے عبارت کی تصحیح، ضبط و اتقان کا خیال رکھے، متن کی تفصیلی تشریح کرے اور سند و متن کی ہر آسان و مشکل چیز کی وضاحت کرے۔ اس طریقے سے طالب علم اسماء الرجال، طبقاتِ محدثین، سند و متن میں موجود علل، الفاظ کے معانی، متونِ حدیث میں موجود مشکل مقامات اور فقہاء کے اختلافات سیکھ جاتا ہے۔ اس طریقۂ تدریس میں تفصیلی شرح اور کامل وضاحت ہوتی ہے۔
اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اصولِ ستہ میں سے کسی کتاب کو بھی اس طریقے کے مطابق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین پہلے سند سے خالی متون طلبہ کو پڑھاتے ہیں، پھر اسی منہاج کو سامنے رکھتے ہوے کتبِ اصول میں سے چند ابواب پڑھاتے ہیں، جس سے علم اور اس کے متعلقات کا طالب علم کے سامنے واضح تصور آجاتا ہے اور فہمِ حدیث کی مکمل مشق ہو جاتی ہے۔ عام اساتذہ اس حوالے سے بہ تدریج آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اربعینِ نووی، تہذیب الاخلاق، ریاض الصالحین اور بلوغ المرام پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ’’مشکاۃ المصابیح‘‘ اور آخر میں جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور تمام کتبِ اصول کی تدریس ہوتی ہے۔
قسم دوم:
طالب علم استاد کے سامنے موطا، اصولِ ستہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ پڑھے۔ استاد کلمات کے زیر زبر کا خیال رکھے، مشکل مقامات حل کرے، روات کے ناموں، کنیتوں، صفات اور نسخوں کے اختلافات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسانید و متون کی ہلکے پھلکے انداز میں تشریح کرتا جاے۔ حدیث پڑھنے کا یہ طریقہ مضبوط اور بہت عمدہ ہے۔ یہی طریقہ محدثین کے ہاں رائج رہا ہے۔ اس میں اعتدال ہے۔ بڑے محدثین کا طریقۂ تدریس بھی یہی تھا۔ ان کی یہ مختصر تشریحات متونِ حدیث کے ساتھ نقل ہوتی آئی ہیں، جنھیں ’’مدرجات‘‘ کہا جاتا ہے۔
- شیخ عابد سندھی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کتبِ ستہ روایت و درایت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوے چھ مہینوں میں ختم کرتے تھے۔
- مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے شاگرد و مرید احمد ابو الخیر مکی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے اپنے استاد مولانا محمد اسحاق دہلوی سے صحیح بخاری دس سے زیادہ دنوں میں پڑھ کر ختم کی۔
- حافظ عبد الحي کتانی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انھوں نے جامع قرویین کی بیرونی محراب میں بیٹھ کر پچاس مجالس میں صحیح بخاری تحقیق و تدقیق کے ساتھ پڑھا کر ختم کی۔ اس میں وہ ابوابِ حدیث اور محلِ استدلال سے متعلق ہر چھوٹی بڑی چیز بیان کرنے کے علاوہ خوب صورت نکات بھی ذکر کرتے گئے۔
یہ سب مثالیں اسی دوسری قسم میں شامل ہیں۔
قسم سوم:
سرد حدیث، یعنی طالب علم استاد کے سامنے صرف حدیث کی قراءت کرتا جاے اور استاد اس پر کوئی تشریح یا تبصرہ نہ کرے۔ قراءت کا یہ انداز پہلے دو طریقوں سے فارغ ہونے کے بعد اختیار کیا جاتا ہے۔ طالب علم متونِ حدیث کا مفہوم جان چکا ہے، اسانید کے مباحث اسے معلوم ہوچکے ہیں، لہٰذا اس اندازِ قراءت میں اس کی دہرائی اور یاددہانی ہو جاتی ہے، اسی طرح نئی اسانید و طرق بھی اس کی نظر سے گزر جاتے ہیں۔
’’سرد حدیث‘‘ کے کئی فوائد ہیں، ان میں چند فوائد ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں:
- کتب حدیث کی حفاظت: اگر محدثین صرف انھی احادیث کو ہی پڑھتے پڑھاتے رہتے، جو انھوں نے اپنے شیوخ سے ضبط و تشریح کے ساتھ پڑھی ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں موجود دیگر تصنیفات ضائع ہو جاتیں، اور بہت سی احادیث نظروں سے اوجھل رہتیں، لہٰذا اپنی عقلِ سلیم کی بہ دولت انھوں نے ’’سرد حدیث‘‘ کے طریقے کو اپنایا اور ہزاروں احادیث سننے اور بے شمار کتب و اجزا پڑھنے کا انھیں موقع ملا۔
- یاددہانی (مذاکرہ): ایک عالم اپنی پڑھی اور سنی ہوئی چیزوں کو بھول سکتا ہے۔ ’’سرد حدیث‘‘ کے ذریعے وہ احادیث یاد رکھ لے گا۔ مذاکرہ ایک معروف طریقہ ہے۔ محدثین ایک ہی مجلس میں ہزار یا اس سے زیادہ احادیث پڑھ لیتے تھے۔
- احادیث کی تلاش میں مدد: سرد حدیث سے متابعات و شواہد کی تلاش میں مدد ملتی ہے۔ کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ فلاں حدیث (مثال کے طور پر) صحابہ میں سے صرف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے یا ائمہ کرام میں صرف سفیان بن عیینہ نے ہی اسے روایت کیا ہے۔ جب ’’سرد حدیث‘‘ کے طریقے کو اپنا کر تصنیفات و اجزاے حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے تو جلد ہی ابوہریرہ کی حدیث کے شواہد اور سفیان بن عیینہ کے متابع مل جاتے ہیں۔
- فہمِ دین (تفقہ): کتابوں کے مصنفین ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب میں نقل کر کے اس پر ’’تراجم‘‘ کی شکل میں مختلف عناوین ذکر کرتے ہیں۔ ’’سرد حدیث ‘‘ سے (ان تراجم کی بہ دولت) حدیث کے دیگر مطالب بھی طالب علم کے سامنے آجاتے ہیں، جس سے اس کے فہمِ دین میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کثرتِ ذکر: ’’سرد حدیث ‘‘ کی وجہ سے خدا کے ناموں اور صفات کا ذکر، اس کی حمد و تسبیح، بزرگی اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنے کا موقع زیادہ حاصل ہوتا ہے۔
- نیکوکاروں سے تعلق: ’’سرد حدیث‘‘ کے دوران میں محدثین کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم، ائمۂ تابعین اور تمام صلحاے امت کے نام آتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے والوں کے دل میں ان کی محبت کے جذبات موج زن ہوتے ہیں اور پھر سیرت و کردار میں ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ محدثین ہی ’’سلف ‘‘ کی پیروی کرتے ہیں اور نیکی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔
- رحم دلی: تلاوتِ حدیث کی مجلس میں مختلف قبیلوں، زبانوں اور دور دراز علاقوں کے لوگ مل بیٹھ کر آپس میں رحم دلی اور محبت بانٹتے ہیں اور دوست بن جاتے ہیں۔ اکیلی یہی رحم دلی شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے۔
سرعت قراءت سے متعلق علما کی راے:
سرعت قراءت کے جواز سے متعلق علما کی راے مشہور ہے۔ تیزی سے پڑھنے کی بنا پر اگر کچھ کلمات و حروف سننے سے رہ جائیں تو اس کمی کو ’’اجازتِ حدیث‘‘ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ ابن صلاح وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھنے والا تیزی سے پڑھے اور دور بیٹھا سامع متن کا کچھ حصہ صحیح نہ سن سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی حدیث کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر سننے والا پڑھی جانے والی چیز کو سمجھ پا رہا ہے تو اس کا ’’سماع‘‘ صحیح ہے۔ مناسب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ’’اجازتِ حدیث‘‘ بھی شامل کر لی جاے تاکہ سننے میں اگر کوئی کمی ہو تو ’’اجازت‘‘ سے پوری ہو جاے۔ امام عبد الرحمان مہدی اور دیگر کئی حفاظِ حدیث سے روایت ہے:
يكفيك من الحديث شمّه
(تمھارے لیے حدیث کی خوش بو کافی ہے)
سلف صالحین اور سرعت قراءت:
خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے مکہ مکرمہ میں کریمہ مروزیہ کے سامنے پانچ دن میں صحیح بخاری پڑھ کر ختم کی اور لوگوں نے ان کی قراءت سے صحیح بخاری سنی۔ شذرات الذہب میں برہان ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بقاعی حنبلی کے حالات میں لکھا ہے کہ انھوں نے علامہ بدر الغزی کے سامنے بیٹھ کر مکمل صحیح بخاری چھ دن میں ختم کی۔ سخاوی فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ چار مجلسوں میں ختم کی اور اختتامی مجلس کو چھوڑ کر صحیح مسلم چار مجالس میں پڑھ کر ختم کی۔ اس سارے عمل میں تقریبا دو سے کچھ زیادہ دن لگے۔۔۔۔ سخاوی کہتے ہیں: سرعت قراءت میں ہمارے شیخ کی جو سب سے بڑی مثال سامنے آئی کہ انھوں سفرِ شام کے دوران میں ظہر اور عصر کے درمیان ایک مجلس میں طبرانی کی معجم صغیر پڑھ کر ختم کی۔ حافظ ابن حجر کی زندگی میں سرعت قراءت کی یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ فرماتے ہیں: ایک جلد کی اس کتاب میں تقریبا پندرہ سو احادیث ہیں۔
مجلس سماع میں کم عمر بچوں کی حاضری:
قراءتِ حدیث کی پہلی دو اقسام حاصل کیے بغیر چھوٹے بچوں کو ’’سرد حدیث‘‘ کی مجالس میں محدثین حاضر ہونے کی اجازت دیتے ہیں، تاکہ انھیں ان مجالس کی برکت حاصل ہو، حدیث سے ان کا تعلق مضبوط ہو، اور محبتِ حدیث میں ان کی اٹھان ہو۔ اس کے بعد وہ ضبط و اتقان اور تشریح کے ساتھ حدیث پڑھ لیں گے۔ حافظ ابو الحجاج مزی کے زمانے میں مجلسِ سماع میں چھوٹے بڑے اور عرب و عجم وغیرہ حاضر ہوتے، ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے اور ایسے بھی ہوتے جو کلامِ نبوی سمجھ نہ سکتے۔ حافظ مزی کے سامنے ہی ان سب کا نام ’’سماعِ حدیث‘‘ میں لکھا جاتا۔ قاضی تقی الدین سلیمان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں کسی نے بچوں کو کھیلنے کی وجہ سے جھڑکا۔ انھوں نے کہا: انھیں نہ جھڑکو، ہم نے انھی کی طرح حدیث سنی۔ تم بھی پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔
کیا ’’سرد حدیث‘‘ کا انداز روایتِ حدیث میں معتبر ہے؟
اگر کوئی سوال کرے کہ روایت حدیث میں ’’سرد حدیث‘‘ کے طریقے پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ: قرونِ اولیٰ میں احادیث و روایات ایسی تیز رفتاری سے پڑھ کر نقل نہیں کی گئیں۔ یہ انداز اس وقت اختیار کیا گیا جب کتابیں لکھی جا چکیں، تصنیفات منظر عام پر آگئیں، اور احادیث و آثار مضبوطی اور عمدگی کے ساتھ محفوظ ہو گئے۔
جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ’’سرد حدیث‘‘ مختلف ذرائع میں سے صرف ایک ذریعۂ علم ہے، جس کا نمبر پہلی دو قسموں کے بعد آتا ہے۔ ان دو قسموں میں ضبط و تصحیح اور تشریح و توضیح کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مولانا یونس جون پوری، شیخ محمد عوامہ، شیخ نور الدین عتر، شیخ عبد الوکیل ہاشمی، شیخ احمد علی سورتی اور شیخ یحیی ندوی وغیرہ ایسے شیوخ ہیں، جو پہلے دو طریقوں سے حدیث پڑھانے میں مشہور ہیں، عموماً ایسے ہی شیوخ سے ہم نے ’’سرد حدیث‘‘ کے ذریعے کلامِ نبوی حاصل کیا۔
ہمارے دوستوں میں حدیث کی قراءت کرنے والے، جن کی قراءت کے ذریعے ہم نے حدیث سنی، بہت زیادہ ہیں۔ ان لوگوں نے اولین درجے میں عربی زبان کی نحو، صرف اور بلاغت پر عبور حاصل کیا اور پہلے دو طریقوں کے مطابق حدیثِ نبوی کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد ’’سرد حدیث‘‘ کی طرف متوجہ ہوے۔ ان میں سے شیخ صفوان داؤدی، شیخ مجد بن احمد مکی، شیخ حامد اکرم بخاری، شیخ احمد عاشور، شیخ محمد بن ابی بکر باذیب، شیخ وائل حنبلی، شیخ عمر نشوقانی، شریف حمزہ کتانی، محقق خالد سباعی وغیرہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں محدث محمد زیاد تکلہ، محقق محمد بن عبد اللہ الشعار اور فقہ و اصول کے ماہر عبد اللہ التوم سب سے زیادہ تیز پڑھتے ہیں۔
یہ سب نحو و لغت میں دستگاہ رکھتے ہیں، غلطی و خطا بچتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں بھی درست کرتے ہیں۔